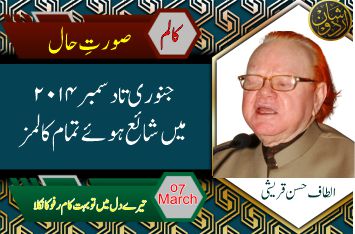افسانہ
ایک اور دَریا
نیلم احمد بشیر

ek or darya
afsana
pakistani prison in india
سکینہ کے کانوں میں کسی کے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ آنکھیں موندے موندے اُس نے حیرت سے سوچا:
’’مَیں مر چکی ہوں، تو مجھے آوازیں کیسے سنائی دے رہی ہیں؟ کیا انسان مرنے کے بعد بھی سن سکتا ہے؟ کیا پتا یہ فرشتوں کی آوازیں ہوں۔ شاید مَیں جنت میں پہنچ چکی ہوں یا ممکن ہے دوزخ میں۔‘‘
وہ اِنھی خیالات میں غلطاں و پیچاں تھی کہ یک دم کسی نے اُس کی پسلیوں میں ٹہوکا دے کر ہلا دیا۔ سکینہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔
’’اوئے اے تے زندہ اے۔‘‘ (اوئے یہ تو زندہ ہے)
ایک مردانہ آواز نے اُسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جان کر اُس کے دل میں یک دم ایک خنجر سا کھب گیا کہ وہ اَبھی تک زندہ تھی، مری نہیں۔
اُف اللہ! تو کیا مَیں دوبارہ اِس ظالم دنیا میں واپس آ چکی ہوں۔ یا اللہ! تُو نے مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ اُس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
بےہوش ہو جانے سے پہلے کا منظر اُس کی آنکھوں کے آگے فلم کی رِیل کی طرح چلنے لگا۔ وہ اِرادے کے مطابق قدم بڑھانا چاہ رَہی تھی، مگر پاؤں من من کے ہو کر زمین میں گڑ گئے تھے۔
بالکل سامنے بہنے والا نیلا نیلا، چوڑا، اُچھلتا کودتا نیلم دریا منہ زور ہو رہا تھا۔
جب اُس کی بپھری ہوئی موجیں بار بار پتھروں سے سر پٹختیں اور پھر آگے جا کر سفید جھاگ میں تبدیل ہو کر سکون سے بہنے لگ جاتیں، تو منظر بہت خوبصورت ہو جاتا۔
’’کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جو کرنے آئی ہے کر۔‘‘ دریا غصّے سے دھاڑا۔
سکینہ سہم گئی اور پل بھر کو اُس سے آنکھیں پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ مگر اب اِس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ اُسے دریا سے ہم آغوش ہونا ہی تھا کہ پیچھے جانے کو اَب کچھ بچا نہ تھا۔
واپسی کی سب راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ ساس، نند اور اُس کے اپنے شوہر سرور نے اُسے بانجھ ہونے کے طعنے دے دے کر اُس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اِسی لیے تنگ آ کر اُس نے دریا کی طرف ہمدردی سے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ اُسے امید تھی کہ وہ اُسے مایوس نہیں کرے گا۔ آ
خر یہ اُس کا اپنا دریا تھا، اُس کے بچپن کا دوست، اُس کا بیلی۔ اِس کے کنارے کھیل کود کر ہی تو اُس نے جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھنا سیکھا تھا۔
مگر دوست نے تو اُس کے ساتھ غیروں والا سلوک کر کے اُسے دھتکار دِیا تھا۔ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟
اُس نے کرب سے سوچا۔
’’اوئے اوئے چلو اُٹھاؤ اِسے۔‘‘ اُسی آواز نے کسی کو حکم دیا، تو چند ہاتھوں نے اُس کے جسم کو اُٹھا کر الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔
’’یہ زنانی دریا میں بھلا کیا کر رہی تھی؟‘‘
’’شاید گر گئی ہو؟‘‘
’’لگتی اُس پار کی ہے، ہماری طرف کی نہیں۔‘‘
وہ مختلف آوازیں سن رہی تھی، مگر اُس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اَب اُس کا کیا ہو گا؟ کچھ ہی دیر میں اُس پر غنودگی چھا گئی۔
جب آنکھ کھلی، تو اُس نے دیکھا وہ اَسپتال میں ہے۔ اسپتال والوں نے اُس کے پیٹ سے پانی نکالا۔ ہوش میں لائے، تو اُسے معلوم ہوا کہ اب وہ سرحد پار کے ملک میں ہے جہاں اُس کا اپنا کوئی نہیں تھا اور وُہ کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔
اگلے دن اُسے بڑے بڑے فوجی افسروں کے سامنے پیش کیا گیا جنہوں نے اُس پر تابڑ توڑ سوالات کی بوچھار کر دی۔
’’ہاں بی بی! بول تُو کون ہے اور سرحد کے اِس پار کیا کر رہی ہے؟ تجھے کس نے بھیجا ہے؟‘‘
’’مَیں کچھ نہیں جانتی جی۔ مَیں نے تو دریا میں چھلانگ لگائی تھی۔ مجھے نہیں پتا مَیں یہاں کیسے پہنچ گئی ہوں۔‘‘ وہ گھگھیانے لگی۔
اُسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آس پاس کھڑے باوردی سپاہی اُس کے ساتھ کسی قسم کا لحاظ کرنے والے نہیں تھے۔ وہ تو محض اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔
’’تجھے کچھ نہیں پتا؟ او بی بی تُو جانتی نہیں کہ تُو اِس وقت بھارتی علاقے میں ہے۔ سچ سچ بتا دے ورنہ ‘‘
ایک حوالدار نے اُسے سختی سے جھنجھوڑا۔ سکینہ نے خوف سے اُن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنی کہانی سنائی، بتایا کہ گھر میں کوئی عزت نہ تھی، سو اُس نے سوچا شاید زندگی سے فرار میں ہی قرار مل جائے۔ اُس نے دریا کی ایک موج بن جانے کی خواہش میں سوچے سمجھے بغیر چھلانگ لگا دی تھی اور بس۔
مگر کوئی اُس کی کہانی پر یقین کرتا نظر نہ آ رہا تھا۔
’’ معاف کر دیں جی، مَیں واپس چلی جاتی ہوں۔ پتا نہیں تھا۔ مجھے میرے گاؤں بھیج دیں۔‘‘
’’جناب! یہ مجھے کوئی پاکستانی جاسوس لگتی ہے۔‘‘ ایک سپاہی نے اُس کے سراپے پر نظر ڈالی۔
’’جسوس!‘‘ سکینہ کو جھرجھری سی آ گئی۔
’’نہ جی نہ، مَیں تو سکینہ ہوں جی۔ مظفرآباد کے پرلی طرف کے چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی۔ مَیں کوئی جسوس وسوس نہیں ہوں جی۔‘‘ سکینہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔
’’کس نے بھیجا ہے تجھے؟ کسی ایجنسی نے یا کسی آتنگ وادی گروپ نے؟‘‘
’’چلو چلو فی الحال اِسے حوالات میں بند کر دو۔ مقدمہ چلے گا، تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ اِس غیرقانونی طور پر داخل ہونے والی کا کیا ہو گا؟‘‘
سکینہ نے واسطے دیے، اللہ رسول کا نام لیا، تو سپاہی کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔
ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ’’لے بھئی غلام محمد، تیری قوم ہے۔ تُو ہی سمجھا اِسے کہ زیادہ ڈرامے نہ کرے اور چپ کر کے بیٹھی رہے۔‘‘
غلام محمد کھسیانی ہنسی کے ساتھ اُٹھا اور سکینہ کے اردگرد گھوم پھر کے چکر لگانے لگا۔ ’’سوہنی تے بڑی اے۔‘‘ (خوبصورت تو بہت ہے)
غلام محمد نے اپنے ڈنڈے سے اُس کی ٹھوڑی اونچی کی اور اَپنے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔
’’غلطی ہو گئی سرکار! مجھے واپس بھیج دیں۔ وہاں میرا گھر والا انتظار کر رہا ہو گا جی۔‘‘
حوالدار شیکھر نے رجسٹر بند کر دیا اور رَوتی کرلاتی سکینہ کو حوالات میں بند کرنے کا حکم دے کر اُٹھ کھڑا ہوا۔
سرسبز جنگل کے بیچوں بیچ بہنے والا دریا دو دیسوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا۔
اُس کے شفاف پانی میں نہ جانے ایسے کتنے نمکین موتی بھی گھلے ہوئے تھے جو دریا کنارے رہنے والوں نے دوسرے پار رَہنے والے سجنوں کی یاد میں بہائے تھے۔
اب سکینہ بھی اپنے گھر والوں، ہم وطنوں کی یاد میں دن رات روتی تھی، مگر دریا اُس سے دور تھا ۔ حوالات کی کال کوٹھری اندھی، گونگی اور بہری۔
سکینہ دن رات یہی التجا کرتی کہ اُسے اُس کے گاؤں واپس جانے کی اجازت دے دی جائے، مگر اِن لوگوں کی بھی اپنی تکنیکی مجبوریاں تھیں۔
یہ تو سیدھا سادا دَراندازی کا کیس تھا، وہ کیا کرتے۔ سرحد عبور کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اگر اُس طرف سے کوئی کتا بھی غلطی سے بھٹک کر اِس طرف آ نکلتا، تو کوئی دن تک اُس کی نگرانی کی جاتی۔
چھان بین ہوتی کہ کہیں کتے کے ذریعے دشمن کوئی جدید حساس خفیہ آلہ نہ اِستعمال کر رہا ہو۔
دوسری طرف والے بھی تقریباً ایسا ہی کرتے تھے۔ اُن کی طرف سے کوئی بھولا بھٹکا کتا آ نکلتا، تو اُسے برا بھلا کہہ کر وہ بھی اپنے کلیجے ٹھنڈے کر لیتے۔
صرف پرندوں پر ہی دشمن کے ایجنٹ ہونے کا شک نہ کیا جاتا۔ چڑیاں، کوے، تتلیاں آزادانہ سرحد کے اِس طرف والے درختوں، پودوں سے اڑ کر اُس طرف جا بیٹھتیں اور پھدکتی پھرتیں۔ نہ کوئی چڑیا لکشمی تھی اور نہ کوئی سعیدہ، نہ وہ ہندو تھی نہ مسلمان۔ وہ تو بس چڑیا تھی اور خوش قسمت تھی سرحد کے دونوں طرف بلا ویزے آتی جاتی رہتیں۔
سکینہ حوالات کی کھڑکی سے چڑیوں کو سرحد پار اُڑ کر جاتے دیکھتی، تو حسرت سے اُس کے دل میں دراڑیں پڑ جاتیں۔
اُسے دریا پر غصّہ آتا کہ اُس نے اُسے کیوں زندہ چھوڑ دیا تھا؟ وہ کیوں بچ گئی تھی؟
اب اُس کی زندگی کی کسی کو کیا ضرورت تھی؟ دریا تو اُس کا دکھ جانتا تھا۔
اُسے پتا تھا کہ اُس کا دامن خالی تھا، گود ویران تھی۔وہ اَب جی کے کیا کرتی۔
دریا نے اُسے اپنے اندر پناہ دَینے کے بجائے باہر تھوک دیا تھا۔ کیسا وقت آن پڑا تھا کہ وہ بھی دوست نہ رہا۔
حوالات کے تنگ و تاریک بوسیدہ کمرے میں قید گوری چٹی صحت مند جوان پاکستانی عورت چراغ کی طرح جھلملاتی تھی۔
مدتوں گھروں سے دور رَہنے والے سپاہی عورت کے وجود کی خوشبو اَپنے اتنے قریب پا کر خواہ مخواہ بات بےبات اونچا اونچا بولنے اور ہنسنے لگ گئے تھے۔ کبھی کبھی اُن کا اُسے گھورنے کے بعد کوئی ذومعنی جملہ سکینہ کے کان میں پڑ جاتا، تو وہ دِل ہی دل میں ڈر جاتی۔
رال ٹپکاتے، بدصورت تھوتھنیوں والے کتوں سے اُسے ہمیشہ ہی خوف آتا تھا، مگر اب کیا کرتی؟ کتے بہانے بہانے سے اُس کی کال کوٹھری کے قریب آ کر بھونکنے اور چکر لگانے لگے تھے۔
ایک روز کچھ عجیب ہوا۔ سکینہ سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔
کوئی اُس کے علاوہ بھی اِس کے کمرے میں موجود تھا۔
’’غلام محمد! تم اِس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟‘‘
سکینہ نے آدھی رات کے بعد اپنے کمرے میں کسی وجود کو پا کر اَپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی۔
’’تسلی رکھ سکینہ بی بی! او مَیں تو تیرا ہمدرد، تیرا اَپنا ہوں۔ اِن سالوں کی بری نظر سے تجھے اب تک مَیں نے ہی تو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ جھلیے تجھے کیا پتا؟‘‘ اُس نے نرمی سے کہا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔
’’اچھا!‘‘ سکینہ نے فوراً ہی یقین کر لیا۔ ’’شکریہ، بھائی غلام محمد! تُو تو میرا اَپنا ہی ہے نا ۔ بھائی مَیں یہاں سے کب چھوٹوں گی؟ مجھے چپکے سے سرحد پار کروا دَو نا۔. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔‘‘
سکینہ دل کی بات فوراً زبان پہ لے آئی۔
’’او ڈرنے کی کیا بات ہے، سکینہ! میرے ہوتے ہوئے تُو بس فکر نہ کر۔‘‘
’’اچھا بھائی، تیری مہربانی۔‘‘ سکینہ نے چادر اَپنے اوپر اور کَس کے لے لی اور تشکر بھری نظروں سے اپنے ہمدرد کو دیکھنے لگی۔
’’اچھا ایک بات سن ذرا۔ اِدھر کو آنا میرے پاس۔‘‘
غلام محمد نے اپنے دونوں بازو کھول دیے اور عجیب عجیب نظروں سے اُس کی طرف دیکھنے لگا۔
سکینہ نے چونک کر اُس کی طرف دیکھا، وہاں غلام محمد نہیں، بلکہ ایک بدصورت تھوتھنی والا کتا ہانپتا ہوا رَال ٹپکا رہا تھا۔ ہمدرد دوست کا دور دُور تک پتا نہ تھا۔
سکینہ جھجھک کر پیچھے ہٹی اور چیخنے کی کوشش کی، مگر غلام محمد نے اُس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اُسے خاموش کر دیا۔
کتے کے مضبوط طاقتور بپھرے ہوئے وجود کے آگے اُس کی اپنی ہستی بےمعنی ہو گئی۔
کتے نے اپنے شکار کو بھنبھوڑا، جھنجھوڑا اور پھر ریزہ ریزہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔
باہر جنگل سر جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا۔ دَریا اپنی لہروں کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ ستارے اپنی خمار آلود آنکھوں کو کبھی کھولتے اور کبھی جھپکتے تھے۔
سب مصروف تھے، کسی کے پاس فرصت نہ تھی کہ وہ سکینہ کی مدد کو آئے اور اُسے کسی حملہ آور سے بچائے۔
اِس واقعے کے بعد سکینہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اُس سے کوئی بات کرتا، تو سفید پھیکی آنکھوں سے اُسے دیکھنے لگتی یا یونہی بیٹھی ناخنوں سے فرش کریدتی رہتی۔
اُسے پتا چل گیا تھا کہ اُس پر ایک بہت بڑا مقدمہ بن چکا۔ جلد چھٹکارا ملنے کی کوئی اُمید نہیں ہو سکتی۔
اب اُسے بڑے شہر کے کسی بڑے جیل خانے میں بھجوا دِیا گیا تھا۔ یہاں اُسے اپنے مقدمے کے فیصلے تک ٹھہرنا تھا۔
جیل کے زنانہ حصّے میں ہر دم اپنی سوچوں میں گم چپ رہنے والی پاکستانی عورت بھارتی قیدی عورتوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی جا رہی تھی۔
وہ سوچتیں وہ یہاں کیوں اور کیسے پہنچی؟اُن سے کچھ مختلف بھی دکھتی تھی۔
کبھی وہ فرش کو ناخنوں سے کریدتی اور کبھی نماز پڑھ کر زور شور سے دعائیں مانگتی نظر آتی۔ عورتیں ایک دوسرے سے کھسر پھسر کرنے لگ جاتیں۔
اُنھیں کبھی کبھار اُس پر ترس بھی آتا، کیونکہ اُس کی کوئی ملاقات کبھی نہ آتی تھی۔
چند ایک آہستہ آہستہ اُس سے مانوس ہو کر اُس کے قریب جانے لگیں ۔ اُس کی اسیری کے بارے میں اُس سے سوال جواب کرنے لگیں، تو سکینہ کا بھی کچھ دل لگنے لگا۔
اُس روز جیل میں درگا دیوی کی پوجا کا بہت زیادہ پرساد آیا تھا۔
ایک تھالی سکینہ کو بھی ملی تھی جسے اُس نے کلمہ پڑھ کر کھا لیا۔ اُس میں موتی چور کے لڈو تھے جو اُسے ہمیشہ بہت اچھے لگتے تھے، مگر کھاتے ہی اُس کی طبیعت کچھ عجیب سی ہو گئی ۔
وُہ باقی عورتوں کو کھاتے پیتے، مسکراتے دیکھتے، حسبِ معمول اپنے پیر کے ناخن سے فرش کریدنے لگی۔
یکایک اُسے لگا زمین سے ایک ہری ہری کونپل پھوٹ رہی ہے۔ بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال اُس کے ذہن میں لپکا، تو وہ گھبرا کر اُٹھ کھڑی ہوئی۔
’’اوہ خدایا!‘‘ اُس نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ یہ کونپل کہیں اور سے نہیں، اُس کی اپنی کوکھ سے پھوٹ رہی تھی۔ ’’کیا ایسا ہو سکتا ہے؟‘‘ لیکن وہ تو بانجھ تھی۔ تو کیا اِس کا مطلب تھا کہ وہ بانجھ نہیں تھی۔ یونہی سسرال کے طعنے کھاتی رہی۔
اِس احساس نے اُسے خوشی سے اتنا نہال کر دیا کہ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اُس کا ماں بننا کن حالات کے تحت ممکن ہوا تھا۔
اُسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اِسے قدرت کا انعام سمجھے یا سزا؟ لیکن مَیں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، سوائے خودکشی کی کوشش کے۔
وُہ بھی پوری تو نہیں ہوئی، تو سزا کس بات کی؟
یہ نئی نرم، سبز پھوٹتی کونپل سورج کی پہلی کرن کی طرح اُس کے وجود میں اُجالا بھر رہی تھی۔
سکینہ کو ایک دم ڈر سا لگنے لگا۔ اب کیا ہو گا؟
اِسی شش و پنج میں چند ہفتے اور گزر گئے۔ اُس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ساتھی قیدی عورتوں نے اپنے اپنے اندازے لگا کر اُس سے معلومات حاصل کرنا چاہیں، مگر سکینہ خاموش رہی۔
ایک دو نے طنزیہ انداز میں چھیڑا اَور ایک دو نے بدھائی بھی دی، مگر سکینہ چپ رہی۔
جیل کی سب سے بزرگ عورت مدھومیا کو خبر ملی، تو وہ سکینہ کے پاس چلی آئی۔ اُس سے پیار سے پوچھنے لگی کہ ماجرا کیا ہے؟
مدھومیا نے سکینہ کی رام کہانی سن کر باقی سب کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وُہ سب اپنی بارکوں میں چلی گئیں۔ مدھومیا کی بزرگی کی وجہ سے اُس کے آگے کوئی بھی زیادہ بک بک نہیں کرتی تھی۔
’’پیٹ سے ہے ری پاکستانی؟‘‘ ایک عورت نے پاس آ کر اُس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ اُسے زیادہ تر عورتیں ’’پاکستانی‘‘ کہہ کر ہی بلاتی تھیں۔
سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں چند اور بھی اُس کے اردگرد جمع ہو گئیں ۔سوالات کی بوچھار کر دی۔
’’ارے تو پھر کیا ہوا۔ پیٹ میں بچہ ہے اور بھولی بنتی ہے۔‘‘ ایک نے کڑوا تیز جملہ بولا، تو باقی سب قہقہہ مار کے ہنسنے لگیں۔
’’چلو دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے۔‘‘ مدھومیا نے سب کو ڈانٹ کے بھگا دیا اور سکینہ کو پچکارنے لگی۔
’’تُو فکر نہ کر بٹیا۔ یہ سالی حرام زادیاں تو یونہی بکواس کرتی رہتی ہیں۔ برسوں سے اِس جیل میں پڑی سڑ رہی ہیں نا۔ تو بس یونہی دل جلانے کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ تُو برا نہ ماننا اِن کا۔‘‘
’’مَیں خوش بھی ہوں اور پریشان بھی میا۔‘‘ سکینہ نے میا کا ہاتھ پکڑ لیا۔
’’تُو اگر چاہے، تو اِس کی خلاصی بھی کروائی جا سکتی ہے۔‘‘ مدھومیا نے کان پاس لا کر سرگوشی کی۔
’’اِس جیل میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔‘‘
’’نہیں میا! مجھے خلاصی نہیں چاہیے۔ یہ بچہ میرے بےقصور ہونے کا ثبوت ہے۔
میری آئندہ زندگی کے ساتھ کا رشتہ ہے۔ اِس کے سہارے مَیں باقی جیون کاٹ لوں گی۔‘‘
سکینہ نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دھیمے انداز میں جواب دیا۔
’’مگر بٹیا! یہ بلاتکار کا بچہ ہے۔ آخر تُو دنیا والوں کو کیا جواب دے گی؟‘‘
میا نے اُسے حقیقت کا احساس دلانے کی کوشش کی۔
’’میا! یہ بچہ صرف میرا ہے، کسی اور کا نہیں۔ مَیں ہی اِس کی ماں اور باپ ہوں۔ حرام حلال کا مجھے نہیں پتا۔ بس یہ میرا بچہ ہے اور کسی کا اِس پر کوئی حق نہیں۔‘‘ سکینہ مضبوط لہجے میں بولتی چلی گئی۔
اُسے احساس ہوا کہ زندگی میں پہلی بار وُہ کسی انسان، کسی رشتے کے بارے میں اتنی خوداعتمادی سے بات کر رہی تھی۔
اِس سے پہلے تو اُس کی زندگی اور اُس کے معاملات کے فیصلے دوسرے ہی کرتے چلے آئے تھے۔ وہ تو بس خاموش تماشائی بن کر ہی جیتی رہی تھی۔
’’مَیں اِسے پالوں گی۔ اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اِسے مجھ سے کوئی چھین نہ سکے گا۔ اللہ نے مجھے میری تنہائیوں کا سہارا دَے دیا ہے۔ یہ میرے اپنے جسم کا ٹکڑا ہے۔ مَیں اِسے کیسے ختم کر دوں؟‘‘
سکینہ کی بات چند ہی روز میں ساری جیل میں پھیل گئی۔ جیل کے اعلیٰ حکام کو بھی علم ہو چکا تھا کہ پاکستانی قیدی کی کہانی میں مزید الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔
اُس کے مجرم غلام محمد کے بارے میں اُسے کچھ علم نہ تھا کہ اُس کی پکڑ ہوئی یا اُسے چھوڑ دیا گیا۔ اُس پہ کیس ہوا یا کیس دبا دیا گیا؟ اُسے تو پروا بھی نہیں تھی کہ اُس کے ساتھ کیا ہوا؟
ایک خوشی سی اُس کے لہو میں گردش کرتی رہتی تھی کہ آخرکار وُہ بےمعنی، بےمقصد کے بجائے ایک کارآمد زندگی گزارنے جا رہی ہے۔
وہ زندگی جو اَب کسی کے کام آئے گی۔ اِس کومل کونپل کو سینچ کر وہ ایک تناور دَرخت کی صورت میں دیکھے گی۔
’ماں‘ کا میٹھا بول سنے گی۔ کتنا اچھا لگے گا اُسے یہ سب کچھ۔
اب وہ خود میں ہر چٹان سے ٹکر لینے کی طاقت محسوس کرنے لگی تھی۔ اُسے لگتا تھا کہ وہ اب پہلے والی بزدل، کمزور سکینہ نہیں بلکہ کوئی نئی عورت ہے۔ ولولوں اور اِرادوں سے بھرپور، ہر طرح سے مکمل۔
جیل کی قیدی خواتین اب اُس سے کچھ نرمی برتنے لگی تھیں۔ اُس کی صحت کا خیال رکھا جانے لگا ۔ اُس سے زیادہ مشقت کے کام بھی نہ کروائے جاتے۔ کبھی کبھار کوئی دل جلی یہ کہہ کر طنز بھی کر جاتی
’’مسلی کے پیٹ میں مسلے کا ہی بیج ہے، تو پھر پریشانی کیسی؟ اپنا ہی خون ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ کم از کم کسی ہندو پرش کو تو اِس پاپ کا ملزم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔‘‘
سکینہ یہ سن کر خاموش رہ جاتی۔ اُس کے مقدمے کا فیصلہ تو التوا میں ہی پڑتا چلا جا رہا تھا۔
نو چاند چڑھتے ڈھلتے دیکھتے سکینہ کے جسم میں کتنی تبدیلیاں آ چکی تھیں ۔ بالآخر وہ مبارک دن بھی آ ہی گیا جس روز سکینہ کی سبز کونپل پھول بن کر ہمیشہ کے لیے اُس کے دامن میں مہکنے کے لیے چلی آئی۔
سکینہ نے اُس پھول کا نام مبین رکھا ۔یہ اُس کی ماں کا نام تھا۔ ماں سکینہ کو بہت یاد آتی تھی۔ پتا نہیں کس حال میں تھی وہ؟ کتنے دُور ہو گئے تھے پیار بھرے رشتے اُس سے، مگر اب یہ جو نیا رشتہ اُس کی زندگی میں آیا تھا، اُسے سب سے توانا، خوبصورت اور اَہم محسوس ہونے لگا تھا۔
’’یہ میری ماں، بہن، سہیلی، بیٹی سبھی کچھ ہے۔ میری پیاری مبین۔‘‘ سکینہ اپنی ننھی بٹیا کو چوم چوم کر نڈھال کر دیتی۔ جیل کی ساتھی عورتیں اُس کی دیوانگی پر ہنسنے لگ جاتیں۔
’’اِسے لے کر جائے گی، تو گھر والوں سے کیا کہے گی؟‘‘ کبھی کبھار کوئی اُسے حقیقت کی دنیا میں گھسیٹ لاتی، تو سکینہ پل بھر کو ساکت ہو جاتی۔
’’میرا سرور بہت اچھا ہے۔ بڑا پیار ہے اُسے مجھ سے۔ بس مَیں اُس کی گود میں بچی کو ڈال کر کہوں گی۔ یہ ہماری بچی ہے۔ ہم دونوں کی۔ شاید وہ، اُس کا دل نرم ہو جائے۔‘‘
’’اگر تجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، تو اُسے چھوڑ کر دریا میں کیوں کودی تھی؟‘‘ کسی نے فقرہ چست کیا۔
دوسری بھی ہنسنے لگیں۔ سکینہ خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی۔ واقعی کہتی تو یہ ٹھیک ہیں۔ پتا نہیں وہ سچ مچ مجھ سے پیار کرتا بھی تھا یا بس میرا وَہم تھا۔
دن گزرتے گئے۔ سکینہ کا کیس لمبا اور پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو مبین پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی۔ساری جیل والیاں اُس سے پیار کرنے لگی تھیں۔
کوئی اُس کی ماسی تھی تو کوئی بوا۔ نانی تو کوئی دادی۔ بیٹی کا خوبصورت ساتھ پا کر سکینہ کو جیل بھی گھر کی طرح لگنے لگی تھی۔ مگر کبھی کبھار نہ جانے کہاں سے اڑ کر کوئی چڑیا یا کوا جیل کی منڈیروں پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرنے لگتا، تو سکینہ کے دل میں ہوک سی اٹھتی۔
’’کیا خبر یہ میرے دیس سے آیا ہو؟ کوئی سندیسہ لایا ہو ۔ کیا خبر مجھے کوئی سرحد پار یاد کرتا ہو ۔ میرا اِنتظار کرتا ہو۔‘‘
ماں کے کبھی کبھار بھول بھٹک کے آ جانے والے خطوں سے اُسے یہ تو پتا چل ہی گیا تھا کہ اُس کا ابا اِس دنیا میں نہیں رہا تھا مگر اماں نے سرور اَور باقی سسرال والوں کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس حال میں ہیں اور اُس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
اُس نے جب بھی پوچھا، اماں اُن کا ذکر ہی گول کر گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں نے اُس کی مبین کی خبر سن کر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔
کبھی اُس کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ یوں جیسے اُس کا ذکر نہ کر کے اُس کے وجود ہی سے انکار کر رہی ہو۔ سکینہ کا دل کڑھتا، مگر پھر وہ سوچتی۔ اماں جب مبین کا چاند سا مکھڑا دیکھے گی، تو خود ہی اُس پر فریفتہ ہو جائے گی۔
مگر نہ جانے وہ مبارک دن کب آئے گا جب مبین اور مَیں اپنے پاک وطن کو لَوٹ سکیں گی۔
’’سکینہ بی بی! یہ تمہارے دیس سے آئے ہیں، برنی صاحب۔ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔‘‘ ایک روز جیلر نے اُسے اپنے دفتر بلوا بھیجا۔
اُس نے دیکھا کرسی پر ایک ادھیڑ عمر کا شفیق چہرے والا شخص بیٹھا اُسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔
’’سلام صاحب جی!‘‘ اُس کا ہاتھ بےاختیار ماتھے تک چلا گیا۔
اُس کے ساتھ کھڑی مبین ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر سکینہ کے پہلو میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔
’’یہ ہے تمہاری بیٹی؟‘‘ برنی صاحب نے اُس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔
’’جی صاحب جی، سلام کر مبین اِنھیں۔‘‘ سکینہ نے مبین سے کہا۔
’’دیکھو سکینہ! مَیں تمہارے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ مجھے تم نے ہر بات صاف صاف بتانی ہے۔ کچھ بھی چھپانا نہیں۔‘‘
’’جی صاحب جی!‘‘ سکینہ نے نظریں جھکا کر بےاختیار ناخن سے فرش کو کریدنا شروع کر دیا۔
شاید آزادی کی کوئی کونپل پھوٹنے والی ہو۔
اُس کے دل میں خوش رنگ غنچے سے چٹخنے لگے۔ شاید اب مَیں گھر جا سکوں۔ اُس نے سوچا۔
’’صاحب جی! مَیں کب گھر جاؤں گی؟ پانچ سال ہو گئے مجھے یہاں بند ہوئے۔‘‘
’’دیکھو سکینہ! یہ انسانی حقوق کی ایک تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔
مَیں اخبار کا صحافی ہوں، اِن کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں۔
ہم لوگ تمہیں جلد سے جلد رہائی دلوانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ تمہاری اِس بچی کا ہے ۔‘‘ برنی صاحب کے ساتھی نے کہا۔
’’بڑے دن ہو گئے ہیں جی صاحب جی گھر گئے ہوئے۔‘‘ سکینہ کی آواز بھرانے لگی۔
’’پانچ سال!‘‘ جیلر لیڈی نے برنی صاحب سے انگلش میں کچھ کہا اور پھر آگے کی گفتگو انگلش میں ہی ہونے لگی۔ سکینہ نے اندازہ لگا لیا کہ گفتگو اُس کی بیٹی مبین کے بارے میں ہی ہو رہی ہے۔
’’تو میڈم جی مسئلہ کیا ہے؟ سکینہ نے بھولپن سے جیلر لیڈی سے سوال کیا۔
’’مبین میری بیٹی ہے، مَیں نے اِسے جنا ہے۔ یہ میرے بدن کا حصّہ ہے، کوئی غیر تو نہیں۔‘‘
’’تجھے کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ تیری بچی بھارتی شہری ہے اور تُو پاکستانی۔
یہ وہاں نہیں جا سکتی اور نہ ہی قانونی طور پر رہ سکتی ہے۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟‘‘
’’تو پھر ٹھیک ہے میڈم جی! مَیں ساری عمر اِسی جیل میں گزار دُوں گی۔ اگر کسی نے مجھے اور مبین کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، تو مَیں اپنی جان دے دوں گی۔‘‘
سکینہ نے جذباتی انداز میں مبین کو اَپنے ساتھ چمٹا لیا اور آنسو بہانے لگی۔
اُس رات دال روٹی کھاتے ہوئے سکینہ کو بار بار اَیسا لگ رہا تھا جیسے اُس کے حلق میں نوالہ پھنس رہا ہو۔
کچھ نگلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ پھر بھی زبردستی کھانا کھاتی رہی، کیونکہ اُس کی تقلید میں آ کر مبین بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتی۔ یہ سکینہ کو گوارا نہ ہوتا۔
برنی صاحب کو برسوں سے التوا میں پڑے ہوئے کیس کو حل کروانے میں ازحد دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ اِس لیے وہ اَور اِنسانی حقوق کی ہم خیال تنظیمیں اب اِس کہانی کو کسی انجام تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔
حکومتیں اپنے اپنے سچ پر ڈٹی ہوئی تھیں۔ حقیقتوں کی سنگینی کے نیزے بھالے میدانِ جنگ میں اُتارے جا رہے تھے۔ برنی صاحب انسانیت کا ٹرمپ کارڈ اِستعمال کر کے سکینہ اور اُس کی بیٹی کو بازی جتوانا چاہتے تھے۔
سکینہ مبین کو یہ یاد دِلاتی رہتی کہ وہ مسلمان ہیں۔ اُن کا دھرم یہ نہیں ہے جو جیل والیوں کا ہے۔
جب سے مبین نے پاکستان واپس جانے، اپنے خاندان سے ملنے کی باتیں سنی تھیں، اُس کا ننھا سا دل مشتاق اور حیران حیران سا رہنے لگ گیا تھا۔
وہ سوچتی کتنا سندر ہو گا آخر میری ماں کا وہ دیس جس کی یاد میں وہ تڑپتی ہے ۔
وَاپس جانے کو بےقرار ہوتی ہے۔ اُسے اچھا لگتا، جب وہ سوچتی کہ ایک اور جہان اُس کا منتظر ہے کہ وہ آئے اور اُس میں سما جائے۔ اُس کا حصّہ بن جائے۔
مبین جیل میں ہی بڑی ہوئی تھی، اِس لیے وہ اَپنے اردگرد ہونے والی پوجاپاٹ میں تلک لگوا کر باقاعدہ حصّہ لیتی۔ بھجن گاتی، تو سکینہ اُسے نہ روکتی۔ ایک تو اِس طرح مبین اُس ماحول کا حصّہ بن کر خوش تھی، دوسرے یہ کہ جیل کی دیگر قیدی عورتیں بھی اُسے اپنی بچی ہی کی طرح سمجھتی تھیں۔
اگر وہ اُسے اُن سے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کرتی، تو مبین کا وہاں رہنا اتنا آسان نہ رہتا ۔اِنھیں کئی قسم کی مشکلات اور تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا۔
سکینہ اپنے طور پر، دل ہی دل میں گاؤں کے مولوی صاحب کے سکھائے ہوئے سبق کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہتی تاکہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون تھی؟ ہے، کہاں سے آئی اور کہاں واپس لَوٹ کے جانا ہے۔
ایک روز جانے کیسے ایک نئے رنگ کا چمکتا سورج طلوع ہوا۔
سکینہ کو وہ خبر مل گئی جس کا اُس نے برسوں انتظار کیا تھا۔
حکومتوں کی مصلحتوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور اِنسانیت جیت گئی۔
سکینہ کا تو خوشی سے برا حال تھا۔ اُس کا جی چاہتا تھا، جیل کے آنگن میں ڈھول بجے اور وُہ دِل کھول کر ناچے۔
مبین اور سکینہ نے جب جیل چھوڑی، تو سب ساتھی عورتیں رو رَہی تھیں۔
کوئی خوشی سے اور کچھ اُن سے بچھڑنے کے غم سے۔ کسی نے ماتھا چوما، تو کوئی سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔
اپنے پاس سے کوئی چیز نشانی کے طور پر دینے کے لیے نکال لائی تھی۔ کوئی اپنا پتا تھما کر خط لکھنے کا وعدہ لے رہی تھی۔
مبین نے تو جب سے آنکھ کھولی تھی، اِس جیل کو ہی اپنا گھر سمجھا تھا۔
وہی عورتیں اُس کی رشتےدار تھیں، اِس لیے وہ سب کو پیار کر کے وعدے کر رہی تھی کہ وہ اُن سے ملنے ضرور آئے گی۔ اُنھیں کبھی نہیں بھلائے گی۔
برنی صاحب کے دفتر نے سکینہ کے شوہر سے رابطہ کر کے بتا دیا تھا کہ سکینہ رہا ہو کر واپس آ رہی ہے، مگر سکینہ کے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے۔
کیا پتا سرور بدل گیا ہو؟ مجھے لینے ہی نہ آئے؟
واہگہ بارڈر عبور کروا کے برنی صاحب نے کچھ دیر انتظار کیا۔
حسبِ توقع سکینہ کا شوہر اُسے لینے نہیں آیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اِدھر اُدھر دیکھتی رہی۔
’’اماں! پِتا جی کہاں ہیں؟ ہم کس کے ساتھ گھر جائیں گے؟‘‘ مبین کے معصوم سوالوں کا سکینہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
یک دم دور سے نظر آنے والا ایک شناسا چہرہ قریب آتا چلا گیا۔ سکینہ کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ اُس کا ننھا بھائی اکرم اُس سے دیوانہ وار لپٹ گیا تھا۔
’’او میرے کاکے، میرے ویر۔ تُو کتنا بڑا ہو گیا ہے۔‘‘ سکینہ نے بار بار اُس کا ماتھا چوما۔ یقین نہ آنے والی کیفیت سے نکلنے کے لیے بار بار اَپنے سر کو جھٹکا دینے لگی۔
یہ وہی چھوٹا بھائی تھا جسے اُس نے گودوں کھلایا تھا۔ اُس کا گو موت صاف کیا تھا، ساتھ سلایا۔ کاکا بھی آپا کو دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔
’’سلام کر مبین! یہ تیرے ماما جی ہیں۔‘‘ سکینہ نے اپنے پیچھے چھپتی مبین کو آگے لا کھڑا کیا۔
’’سلام ماما جی!‘‘ ننھے ننھے ہاتھ ماتھے تک چلے گئے۔
کاکا یوں پیچھے ہٹا جیسے اُسے بجلی کا کرنٹ چھو گیا ہو۔
’’تُو اِس گند کو بھی ساتھ لے آئی ہے۔‘‘ کاکا غصّے سے دانت پیسنے لگا۔
’’مَیں نے تو سمجھا تھا ، صاحب جی، یہ کیا؟ آپ نے تو خط میں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہندوؤں کی بچی بھی ساتھ ہو گی۔‘‘
وہ برنی صاحب کی طرف شاکی نظروں سے دیکھنے لگا۔
’’کاکے یہ ہندوؤں کی بچی نہیں ہے۔ یہ میری اولاد ہے، صرف میری۔
میرا خون ہے یہ، مَیں اِسے کیسے پیچھے چھوڑ کر آ سکتی تھی؟‘‘
سکینہ نے کاکے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر کاکا اُن دونوں ماں بیٹی سے منہ پھیرے کھڑا رَہا، یوں جیسے وہ کوئی غلیظ، کریہہ چیزیں ہوں اور وُہ اِنھیں دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔
برنی صاحب اُسے ایک کونے میں لے گئے اور آدھ گھنٹے تک نہ جانے کیا سمجھاتے رہے کہ کاکا منہ بنا کر اپنی آپا کے پاس چلا آیا اور اُسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر دیا۔
واہگہ بارڈر پر آئی ہوئی خواتین کی این جی اوز کے نمائندوں نے اِن دونوں ماں بیٹی کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا۔ گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دیے۔ پریس والوں نے کھٹاکھٹ تصویریں کھینچیں۔
رِپورٹروں نے نوٹ بُکس سنبھال لیں۔ چند خواتین نے مبین کو بسکٹوں، ٹافیوں اور دِیگر تحائف کے ڈبے دیے۔ اُس کا چہرہ کِھل اٹھا۔
اُسے اپنا نیا وطن پسند آ گیا تھا جہاں قدم رکھتے ہی اُس پر اتنی نوازشات کی برسات ہونے لگی تھی۔
مظفرآباد کی بس سے اترتے ہی مبین نے سوالات شروع کر دیے۔
’’اماں گھر آ گیا۔ اماں ماما ہمیں کہاں لیے جا رہا ہے؟‘‘ سکینہ نے اُسے مختصر جواب دے کر خاموش کرنا چاہا، مگر وہ بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔
جیل کی چار دِیواری سے باہر کی دنیا ایسی ہوتی ہے، اُسے یقین نہیں آ رہا تھا۔
سکینہ بھی برسوں بعد ملنے والی آزادی کی خوشی سے سرشار تیز تیز قدم اٹھائے بھائی کے پیچھے چلتی جا رہی تھی، مگر کاکا تو چپ ہی ہو گیا تھا۔
سوائے ہوں ہاں کے کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔
’’اماں! مَیں تیری بیٹی ہوں نا؟‘‘ مبین نے سوال کیا۔
’’ہاں میری بچی، تُو میری جان ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا۔‘‘
’’مگر ماما تو کہہ رہا تھا مَیں ہندو کی بچی ہوں۔‘‘ مبین نے ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
سکینہ ٹھٹک کر رہ گئی۔
اب وہ دَریا کے قریب سے گزر رَہے تھے۔ سرسبز وادی کی گود میں دریائے نیلم اُسی شان و شوکت، اُسی کروفر سے بہ رہا تھا جیسے پہلے بہتا تھا۔
یہ وہی ظالم ہے جس کی گہرائیوں سے مَیں نے پناہ کے موتی تلاش کرنا چاہے، تو اِس سفاک نے مجھے پناہ دَینے کے بجائے بےرحمی سے دھتکار دِیا تھا۔
سکینہ نے شکوہ بھری نگاہوں سے اُس کی طرف دیکھا۔ پھر اُسے خیال آیا اگر دریا مجھ پر ظلم نہ کرتا، تو مبین کہاں سے آتی؟
میری مبین، میری بچی۔
اِس فرحت بخش خیال کے آتے ہی سکینہ کے چہرے پہ ممتا کا نور پھیل گیا اور مبین کے ہاتھ پر اُس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔
سکینہ کی نظریں بہتے ہوئے دریا پر دوبارہ جا ٹکیں۔ کنارے چلتے چلتے اُسے ایسا لگا جیسے یہ وہ دَریا ہی نہیں تھا جس میں وہ کودی تھی۔
یہ دریا وہ وَالا ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ ہر دریا کے پانی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔
بھنور نئے نئے گول دائروں میں قید ہوتے جاتے ہیں۔ لہریں ہر بار نئے نئے انداز سے اٹھلاتی ہیں اور کنارے چلنے والوں کے عکس لمحہ لمحہ مختلف ہوتے نظر آتے ہیں۔
اب اگر وہ اِس دریا میں قدم رکھتی، تو نہ تو وہی پانی ہوتا، اور نہ ہی وہ مانوس لمحہ جس میں اُس نے پہلے پہل طوفانوں کی زورآوری کو آزمایا تھا، یہ تو کوئی اور ہی دریا تھا۔
مبین نے دریا کنارے اگی ہوئی پیلے پھولوں کی جھاڑی سے ایک پھول توڑ لیا ۔ اُسے ہاتھ میں نچانچا کر خوش ہونے لگی۔ اُسے مسکراتے دیکھ کر کاکے کی تیوری پر بل پڑ گئے۔
خشمگیں نگاہوں سے بچی کو دیکھ کر بولا ’’جلدی کر کڑئیے، کار وِی اپڑنا ایں۔‘‘
(جلدی کرو لڑکی، گھر بھی پہنچنا ہے۔) مبین سہم کر ماں سے چپک گئی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔
سکینہ نے ایک بار پھر دریا کو دیکھا۔ اب اُسے یقین ہو گیا کہ اُسے زندگی بھر ایک اور ہی دریا کا سامنا کرتے رہنا پڑے گا۔
ایسا دریا جو ہمیشہ اُس کے سامنے بچھا رہے گا۔
ہمیشہ اُس کے مدِمقابل ہو گا۔