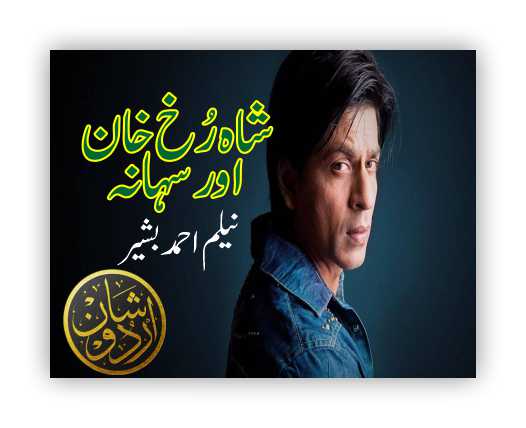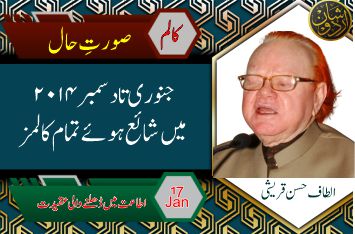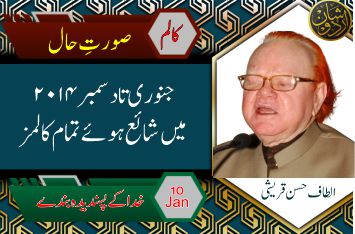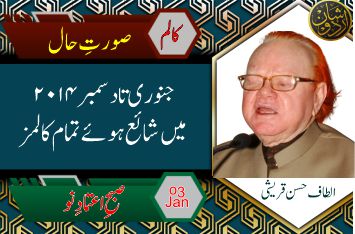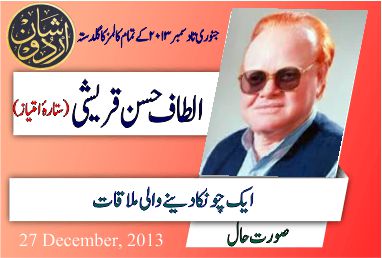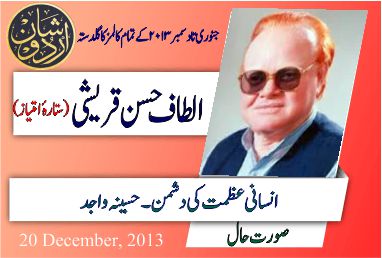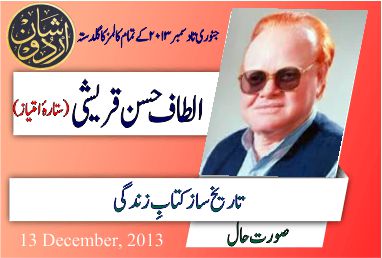افسانہ
شاہ رُخ خان اور سہانہ
نیلم احمد بشیر
ایک ایسی دیوانی کی کہانی جو مرنے سے پہلے اپنے پسندیدہ ہیرو کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی
اِن دنوں مَیں اپنی بیٹی عنبر کے پاس امریکا کی ریاست ورجینیا میں ٹھہری ہوئی ہوں۔
ورجینیا وہ خوبصورت ریاست ہے جہاں ایک زمانے میں کاروں کی نمبر پلیٹوں پر لکھا ہوتا تھا ’’ورجینیا از فار لورز‘‘ (Virginia is for Lovers)۔
اب مَیں نے حالیہ برسوں میں نمبر پلیٹوں پہ ایسا کچھ لکھا نہیں دیکھا۔
شاید اِس لیے کہ امریکا کے حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ ایسے رومانوی خیالات کا ذکر اب نمبر پلیٹوں پہ کرنا مناسب ہی نہیں رہا۔
اب امریکیوں کو ’’فن اینڈ گیمز‘‘ کی جگہ دہشت گردی، جنگوں، ڈیزی کٹر حملوں اور مسلم عسکریت پسندوں (Millitants) جیسے عوامل سے جو نبردآزما رہنا پڑتا ہے۔
ورجینیا چونکہ امریکا کے دارالحکومت شہر واشنگٹن ڈی سی سے جڑی ہوئی ریاست ہے۔
اِس لیے اُس پُرجمال، پُروقار صاف ستھرے شہر کا سنجیدہ کلچر اِس پہ بھی چھایا ہوا نظر آتا ہے۔
پُرشکوہ عمارات، کشادہ سبز باغات، ٹریفک کے منظم بہاؤ والا واشنگٹن ڈی سی وہ خوبصورت شہر ہے ،
جہاں سے حاکمِ دنیا، کم تر ملکوں کے لیے بدصورت فیصلے صادر کرتے ہیں۔
میری بیٹی عنبر یہاں کے ٹاؤن کرسٹل سٹی کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن جاب کرتی ہے۔
اُسے اکثر اپنی اچھی کارکردگی پہ شاباش اور توصیفی اسناد ملتی رہتی ہیں۔
پچھلے دنوں اُس کی تنخواہ میں بھی اچھا خاصا اضافہ کر دیا گیا،
تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے زبردست کھانا کھلایا۔ وہ ہمیشہ ہی مجھ پر دل کھول کر پیسے خرچ کرتی ہے۔
شام کو جب کام سے واپس آتی ہے، تو ہم دونوں ماں بیٹی چہل قدمی کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے خوبصورت پارکوں میں نکل جاتی ہیں۔
مَیں اِس اونچی شانوں والے خوبصورت شہر کی سج دھج اور جاہ و جمال کو دیکھ کر ہمیشہ سوچتی ہوں کاش میرے ملک کے شہر بھی ایسے ہی ہوتے۔
کاش ہم نے کشکول سازی کی صنعت کو فروغ دینے کے بجائے سائنس و ٹیکنالوجی کی محبت کو اَپنا ایمان بنایا ہوتا، تو آج یوں اپنا دیس چھوڑ کر پردیسوں میں بےوطن ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتے۔
پچھلے کچھ دنوں سے شہر ڈی سی میں انڈین فلم سٹارز کے ایک تفریحی شو کا بہت چرچا تھا۔
ٹی وی پہ اشتہار چل رہے تھے، انٹرنیٹ پہ ٹکٹ فروخت کیے جا رہے تھے اور ہر طرف پروموشن پوسٹرز لگے دکھائی دے رہے تھے۔
۴ ستمبر کو “Temptation 2004” کے نام سے کیا جانے والا یہ شو کافی پُرکشش دکھائی دے رہا تھا۔
’’کیوں نہ ہم بھی یہ مزےدار شو دیکھیں؟‘‘
عنبر نے مجھ سے کہا اور سو سو ڈالر کی دو ٹکٹیں خرید لیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پہ بہت خوش تھی۔
مَیں نے بہت سال پہلے امریکا میں اِسی قسم کا امیتابھ بچن شو دیکھ رکھا تھا کہ تب امیتابھ کا دور تھا۔
وہ جوان تھا اور ہم نوجوان، لیکن اب عرصہ دراز سے اِس قسم کا کوئی بھارتی شو دیکھنے کو موقع نہیں مل سکا تھا،
لہٰذا مَیں نے بھی یہ سوچ کر خوشی خوشی حامی بھر لی کہ
’’اچھا ہے چلے چلتے ہیں مزا رہے گا۔‘‘
ہم واشنگٹن ڈی سی کے بڑے سے سٹیڈیم نما ایم سی آئی سنٹر میں ہونے والے اُس شو کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔
اب کوئی مانے یا نہ مانے، بھارتی فلمیں ہم سب کی زندگی کا اہم حصّہ بن چکی ہیں ۔
ہر گھر میں ذوق شوق سے دیکھی جاتی ہیں۔
بھارت، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، یورپ، امریکا جہاں جہاں بھی برِصغیر کے لوگ آباد ہیں۔
بھارتی فلمیں تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں اور یہی حقیقت ہے۔
اگر مَیں یہ کہوں کہ ہمارے مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کے بچوں کو اپنی زبان، تہذیب اور رَسم و رواج کی تعلیم دینے میں بھارتی فلموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو کچھ ایسا غلط نہ ہو گا۔
آج بھارتی فلمیں بین الاقوامی معیار کے مطابق بنتی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں چلتی ہیں۔
ہالی وڈ کے ہم پلہ بالی وڈ سینما نے دنیا بھر میں اپنے مداحین پیدا کر لیے ہیں ۔
اِسی لیے اُن کے فلم سٹارز کے شو اِتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔
اِس شو کے بڑے فنکاروں میں سیف علی خان، پریتی زنٹا، رانی مکرجی، پریانکا چوپڑہ کے نام تھے،
مگر سب سے زیادہ جس نام کے لیے لوگ شو دیکھنے جا رہے تھے، وہ تھا سپر اسٹار اداکار شاہ رُخ خان۔
سالہا سال سے مقبولیت کی سیڑھی پہ اُوپر ہی اُوپر چڑھتے چلے جانے والے شاہ رُخ آج اپنے مداحوں کے لیے نمبر وَن کی حیثیت رکھتے ہیں،
کیونکہ اُس کی اداکاری، شخصیت اور فن نے سبھی کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔
ہم ماں بیٹی اور قریبی شہر بالٹی مور میں رہنے والی میری بھابی فرح تینوں شو دیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔
عنبر کا خیال تھا کہ پارکنگ کے مسئلے کی وجہ سے ہم لوگ لوکل ٹرین سے سفر کریں، تو بہتر ہو گا۔
یہی سوچ کر ہم ٹرین اسٹیشن کی طرف چل دیے۔
نیویارک شہر کی نسبت واشنگٹن ڈی سی کی میٹرو ٹرین اور اسٹیشن بہت صاف ستھرے اور خوبصورت لگے۔
اسٹیشن کی گول چھت اور کنکریٹ میں بنے جیومیٹریکل ڈیزائن کو سراہتے ہوئے ہم کچھ ہی دیر میں ٹرین میں جا سوار ہوئے جس نے ہمیں ایم سی آئی سنٹر کے بالکل قریب ہی اتار دِیا۔
چند منٹوں کی واک کے بعد ہم لوگ بڑے سے اُس سنٹر کے پاس پہنچ گئے۔
جہاں اکثر نامور اَمریکی گلوکاروں کے کنسرٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
سڑک پہ ہم جیسے لوگوں کا جنہیں امریکا میں ’’دیسی‘‘ کہا جاتا ہے۔
ایک ہجوم تھا جو شو کے لیے آیا ہوا تھا۔
اچھے اچھے کپڑے پہنے بوڑھے، بچے، فیشن ایبل لڑکے، لڑکیاں سبھی کے چہرے شو کے خیال سے دمک رہے تھے۔ کوئی کسی کو ہیلو ہائے کہہ کر گلے مل رہا تھا،
تو کوئی موبائل فون پہ کسی آنے والے دوست کو راستہ سمجھا رہا تھا کہ امریکا میں کہیں بھی آنا جانا ہو، ہدایات کے بغیر کوئی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔
ہر طرف رنگ برنگ شلوار قمیص، ساڑھیاں، پتلون قمیص، کڑھائی والے کرتے پاجامے پہنے شائقین کھڑے نظر آ رہے تھے ۔
خاموش امریکی سنڈے، جاندار دیسی اتوار میں تبدیل ہو چکا تھا۔
ہم تینوں ابھی عمارت کے اندر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھیں کہ یک دم ہماری نظر دو خواتین پر پڑی جو ہال میں جانے کے لیے اِسی طرف آ رہی تھیں۔
دونوں پاکستانی لگ رہی تھیں۔ ایک نے دوسری کو سہارا دَے رکھا تھا جو لڑکھڑا کر رُک رُک کر چل رہی تھی۔
جیسے ہی وہ ہمارے قریب آئیں، فرح لپک کر اُن کی طرف بڑھی، سلام کرنے کے بعد کہنے لگی:
’’باجی! یہ سہانہ اور اُس کی بھابی ہیں۔‘‘
مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، سہانہ بالٹی مور وَالی اور یہاں؟
وہ اِس حالت میں کیسے بستر سے اُٹھ کر آ گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
’’کیا! سہانہ یہاں آئی ہے؟‘‘
مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہیں آ یا۔ سہانہ فرح کے شہر بالٹی مور کی رہنے والی تھی جس کے بارے میں فرح دکھ سے بتایا کرتی تھی کہ وہ سرطان کی آخری اسٹیج پر پہنچ چکی ہے۔
ڈاکٹروں نے اُس کے مرض کی تشخیص کے بعد اُس کے کئی اندرونی اعضا کاٹ ڈالے تھے،
مگر کینسر اُسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا اور سارے جسم میں پھیل چکا تھا۔
اُس کا علاج بالٹی مور کے چوٹی کے اسپتالوں میں ہو رہا تھا ،
مگر ڈاکٹر بےبس ہو چکے تھے اور اب اُنھوں نے اُسے لاعلاج قرار دَے کر گھر بھیج دیا تھا۔
ایک مرحلے پہ اُنھوں نے اُس کے کیس کو کینسر سٹڈی کے لیے تحقیقی کالج میں بھی بھیجنا چاہا، مگر سہانہ اور اُس کا شوہر رضامند نہ ہوئے۔
سہانہ گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ چار چھوٹے چھوٹے بچے اُس کی راہ تک رہے تھے۔
اُس کی حالت بتدریج خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کیموتھراپی سے سر کے تمام بال جھڑ چکے تھے،
مگر سہانہ ناامید نہیں تھی۔
ہر وقت اُس کے منہ پہ یہی جملہ ہوتا
’’شاید اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دیں، شاید اُنھیں ایک بچوں کی ماں پہ رحم آ جائے۔‘‘
وہ حوصلہ ہارنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی، لہٰذا ہر وقت زندہ رہنے کی باتیں ہی کیا کرتی تھی۔
فرح بتاتی تھی کہ سہانہ کس قدر زندگی سے بھرپور، شوقین مزاج، ہنسی مذاق کرنے والی ہنگاموں کی دلدادہ لڑکی تھی۔ اُسے اچانک ہی اپنے مرض کے بارے میں پتا چلا تھا۔
اب زندگی کے دیے کی لَو مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ عمر بھر کی نقدی ختم ہو رہی تھی،
مگر حسرتیں ایسی تھیں کہ اُن کا انبار لگتا چلا جا رہا تھا۔
وہ مشکل سے سانس لیتی تھی، مگر پھر بھی گھر میں بچوں کے لیے کھانا بناتی، لڑکھڑاتی ٹانگوں سے اُن کے چھوٹے موٹے کام کرتی اور کہتی جتنے دن اپنے بچوں کے کام آ جاؤں، اچھا ہے۔
اپنی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے اُس میں وطن واپس جا کر ماں باپ، بہن بھائیوں کو بھی آخری بار ملنے کی شدید خواہش پیدا ہو چکی تھی
لیکن وہ پاکستان نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اُس کے گرین کارڈ کا مسئلہ ابھی التوا میں پڑا ہوا تھا۔
اگر وہ چلی جاتی، تو واپس نہ آ سکتی تھی اور وَاپس وہ ضرور آنا چاہتی تھی ۔
اَپنی زندگی کی باقی ماندہ پونجی اپنے بچوں اور شوہر پہ نچھاور کرنا چاہتی تھی۔
گھر بار ااَمریکا میں تھا اور دُوسری طرف اُس کے ماں باپ پاکستان میں بےچَین تھے،
وہ ہر قیمت پہ اُس سے ملنا چاہتے تھے، مگر سر پٹخ رہے تھے،
کیونکہ امریکن قونصلیٹ سے اُنھیں ویزا جاری نہیں ہو رہا تھا کہ اب امریکیوں کو تھرڈ ورلڈ کے مسلمانوں پر اعتبار نہیں رہا۔
اُن کی بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے قدم امریکا کی سرزمین سے دور ہی رہیں۔
امریکا ایک آکٹوپس کی طرح اپنے خوبصورت سہل پُرکشش نظام اور معاشی آسودگی میں جب جکڑ لیتا ہے،
تو اُس کی مضبوط ٹانگوں میں پھنس کر انسان بےبس ہو کر اَپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے۔
اُس وقت تک واپسی کی سب کشتیاں جل چکی ہوتی ہیں۔
سب دوست احباب سہانہ سے ہنسی خوشی فون پہ بات کرتے۔
اُس کی خیریت دریافت کرتے اور ڈرتے اُس دن سے جب سہانہ کی جگہ اُس کا میاں فون اُٹھائے اور کہہ دے کہ اب سہانہ یہاں نہیں رہتی۔
موت ایک وحشی ڈائن کی طرح ہڈیوں کے بالن کے بھڑکتے الاؤ کے گرد قہقہے لگاتی ناچتی پھر رہی تھی اور زندگی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔
سہانہ شاید اپنی زندگی کا آخری تماشا دیکھنے آئی تھی کہ ایک پردہ اُٹھنے والا اور ایک گرنے والا تھا۔
’’تم یہاں کیسے! تمہاری طبیعت کیسی ہے؟‘‘ فرح نے پیار سے اُس کا بازو تھپتھپایا۔
’’طبیعت نے تو ٹھیک ہونا نہیں، مَیں نے سوچا کیوں نہ مَیں بھی کچھ لطف اندوز ہو لوں۔‘‘
اپنے گنجے سر پہ دوپٹے کو ٹکانے کی کوشش کرتے ہوئے سہانہ مسکرانے لگی۔
’’ہاں تو اور کیا!‘‘
مَیں نے بھی کہا
’’اگر تمہارا جی چاہ رَہا ہے، تو شو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ ذرا طبیعت ہی بہل جائے گی۔
ہم تو اپنی سہانہ کو ہر حال میں خوش رکھنا چاہتے ہیں بھئی۔‘‘
سہانہ کی بھابی نے پیار سے اُس کے چہرے پہ گرنے والا ڈوپٹا ہٹایا اور ہم سب دھیرے دھیرے ہال کے اندر جانے لگے۔
’’کیا تم اتنی دیر آرام سے بیٹھ لو گی؟‘‘ فرح نے پھر اپنی دوست سہانہ سے پوچھا۔
’’جب تک بیٹھ سکی، بیٹھوں گی، ورنہ پھر اٹھ کر چل دیں گے اور کیا چلے تو جانا ہی ہے۔‘‘
سہانہ کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی اور میرے کلیجے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔
ہماری نشستیں ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پہ نہ تھیں، اِس لیے ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔
شور اِتنا زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔
روشنی اور آواز کے رنگ برنگ تماشے کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں مشتاق اور دِل بےتاب تھا۔
ہم بھارتی فلموں کے مقبول ترین فنکاروں کو دیکھنے جا رہے تھے۔
مَیں بھی خوش تھی، کیونکہ عمررسیدہ ہو جانے کے باوجود موقع کی مناسبت سے مَیں بھی بچوں کے ساتھ بچی ہو جاتی ہوں اور بڑوں کے ساتھ بڑی۔
شامل ہو جانے میں ہی عافیت ہے، ورنہ وقت کی طرح بچے بھی مجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے ۔
مَیں اکیلی کھڑی رہ جاؤں گی۔
بالآخر شو شروع ہو گیا، پردہ اُٹھا۔ حاضرین نے تالیاں بجا کر آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔
اسکرین پہ فنکاروں کی شو کے لیے تیاری کی ویڈیو دکھائی گئی جس سے لوگ وارم اپ ہو گئے اور خوب تالیاں بجیں۔
انسانی جذبات کے حوالے سے تھیم کو تشکیل کیا گیا تھا، لہٰذا جتنے فنکار اسٹیج پر آتے گئے اُن کے آنے سے پہلے اُن کے ساتھ ایک جذبے کا نام سکرین پر ابھرتا اور پھر غائب ہوتا رہا۔
سب سے پہلے آنے والے فنکار اَرجن رام پال تھے جن کے لیے جذبہ رشک Envy تجویز ہوا تھا اور اُنھیں دیکھا، تو واقعی یقین آ گیا کہ اُن کے لیے یہی نام موزوں تھا۔
سبز روشنیوں میں نہائے ہوئے لانبے قد، کسرتی جسم والے اُس نوجوان اداکار کا حسن کسی یونانی دیوتا سے کم نہ تھا اور حاضرین کی پُرزور ستائش اِس بات کی کھل کر گواہی دے رہی تھی۔
ارجن نے اپنے چند مقبول فلمی گانوں پہ ایک ڈانس گروپ کے ساتھ مہارت سے ڈانس کیا اور مداحوں کی تالیوں کی گونج میں سٹیج سے غائب ہو گیا۔
پردے پر لکھے ہوئے اگلے جذبے کا نام Passion تھا۔
جیسے ہی یہ ایکٹ شروع ہوا، سارا منظر گلابی سا ہو گیا اور مدھر دھنیں فضا میں تیرنے لگیں۔
حاضرین سمجھ گئے کہ پریتی زنٹا آ رہی ہے، لہٰذا اُنھوں نے اِس بھولی صورتیا کا دل کھول کر استقبال کیا۔
پریتی نے خوبصورت مختصر جھلملاتے کپڑوں میں اپنے مشہور گانوں پر ڈانس کیا اور لوگوں کو دیوانہ بنا دیا۔
اب کی بار جو پردہ گرا، تو نئے عنوان کے ساتھ اٹھا۔ Lust لکھا دیکھتے ہی لوگوں کی حسِ ظرافت پھڑکنے لگی۔
سب ہنسنے لگے۔ اِس جذبے کی نمائندگی کے لیے خوبصورت نوجوان اداکارہ پریانکا چوپڑہ اَور سیف علی خان منظر پہ نمودار ہوئے اور اَپنی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنے لگے۔
پریانیکا نے بہت اچھا گایا اور ڈانس کیا۔ سیف نے سٹائلش انداز میں گٹار بجائی اور حاضرین سے مخاطب بھی ہوئے۔ لڑکیاں بار بار We love you Saif!کہتیں، تو وہ بھی فلائنگ کِس پھینک کر جواب دیتے۔
I love you too۔
اِس سے ہال میں جوش بڑھتا چلا جاتا۔ لوگ خوش ہو رہے تھے، تالیاں پِیٹ رہے تھے، رنگ و رَوشنی کا ایک حسین احساس تھا جس کی چمک سے آنکھیں چکاچوند ہوتی چلی جا رہی تھیں۔
رانی مکھرجی سٹیج پر آئیں، تو اُن کے مداحوں نے اُنھیں بھی خوب سراہا اور کئی لوگ اُن کے ڈانس کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈانس کرتے نظر آنے لگے۔
مَیں نے کنکھیوں سے سہانہ کی طرف دیکھا جو عنقریب ایک جیتے جاگتے انسان سے ایک شبیہہ میں تبدیل تو ہونے والی تھی، مگر کائنات کے نظام میں اہمیت رکھتی تھی۔
وہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان کے دروازے کو نیم وا کیے بیٹھی تھی۔
مشتاق اکھیوں سے باہر گلی میں کھیلے جانے والے تماشے سے لطف اندوز ہو رَہی تھی۔
وہ باغِ حیات کی خوشبودار مہکتی روشنیوں سے اپنے لیے نشاط کی چند کلیاں چُن کر دامن میں بھر لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وقت کے دریا میں بہتا پانی کبھی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا۔
سیف علی خان کے بعد پستہ قد والی سانولی سلونی اداکارہ رَانی مکھرجی سٹیج پر آئیں اور کمال فن اور چمکتے ملبوسات کا چمتکار دِکھا کر حاضرین کو دیوانہ کر دیا۔
لوگ اُس کے رقص پہ جھوم اٹھے اور خوب تالیاں بجا کر داد دِی۔
اُن سب فنکاروں کی رخصتی کے بعد ہال پر چند لمحوں کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔
سہانہ کی بھابی نے اپنی نند کی طرف دیکھ کر پیار سے پوچھا:
’’چلیں، تم تھک گئی ہو گی؟‘‘
’’نہیں! جتنی دیر بیٹھ سکی، بیٹھوں گی۔‘‘
سہانہ دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور سٹیج پر نگاہیں گاڑ دیں۔
ایک بچہ زندگی کے میلے میں آخری بار گھوم لینے کے خیال سے خوش تھا اور اندھیرے ہال میں دھیمی دھیمی روشنی پھیل جانے کے بعد پردہ اُٹھتا نظر آ رہا تھا۔
پردے پہ جیسے ہی لفظ Love لکھا نظر آیا، حاضرین کی آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو گئیں،
کیونکہ اُنھیں پتہ چلا گیا تھا کہ اب ون اینڈ اونلی شاہ رُخ خان آ رہے ہیں۔
وہ شاہ رُخ خان جس کے لیے وہ کب سے منتظر تھے۔ سہانہ کسمسا کر پہلو بدلنے لگی۔
شاہ رُخ کو سٹیج پر اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر مجھے قدرے حیرت ہوئی،
کیونکہ اسکرین پر اتنا خوبصورت دِکھنے والا یہ مقناطیسی کشش کا حامل اسٹار کافی درمیانی شکل و صورت اور قد بُت کا مالک تھا۔
اُس کی مقبولیت میں یقیناً اُس کی جاندار اَداکاری اور ہر دلعزیز شخصیت کا بھی ہاتھ ہے،
کیونکہ آج شاہ رُخ جیسی محبت کم ہی فنکاروں کو نصیب ہوتی ہے۔
وہ اَپنے فلم بین مداحوں کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں سب کچھ خوبصورت اور ممکن ہوتا ہے۔
الجھنیں سلجھ جاتی ہیں اور حقیقتوں کی تلخیاں دھواں ہو جاتی ہیں۔
لوگوں نے تالیاں بجا بجا کر اَپنے محبوب اداکار کا سواگت کیا،
تو اُسی لمحے چھت سے ٹپکتے ہوئے دل کی شکل والے سرخ غباروں سے سماں مزید رومانوی ہو گیا۔
لڑکے، لڑکیوں نے جوش کے مارے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور باتوں باتوں میں جب کسی بات پہ بےساختہ انداز میں ماشاء اللہ کہا، تو بہت اچھا لگا۔
وہ حاضرین سے باری باری پوچھتے چلے گئے۔ ممبئی سے کوئی ہے، یہاں پنجابی کتنے ہیں اور پھر آخر میں کہا کیا میرے پاکستانی دوست آئے ہوئے ہیں؟
تو سب پاکستانیوں نے زور شور سے تالیاں پِیٹیں جن میں مَیں بھی شامل تھی۔
اُس وقت شاہ رُخ مجھے بہت اپنا اپنا سا لگا کہ سنا ہے شاہ رُخ پاکستانیوں سے بھی پیار کرتا ہے۔
کرنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستانی بھی تو بڑے ذوق شوق سے اُس کی فلمیں دیکھتے ہیں۔
شاہ رُخ خان نے حاضرین میں سے ایک لمبے تڑنگے سردار جی کو سٹیج پر بلایا،
تو اُنھوں نے وفورِ جذبات میں شاہ رُخ کو گود میں ہی اٹھا لیا اور پیار سے اُس کے ماتھے پہ آئے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔
سارا ہال ہنس ہنس کر داد دَینے لگا۔ لگتا تھا اُس لمحے ساری دنیا خوش تھی اور دُکھ نام کے کسی جذبے سے آشنا نہ تھی۔ سہانہ بھی ہنس رہی تھی۔
اُسے اُس وقت کہاں یاد تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں تماشہ ختم ہو جائے گا۔
روشنیاں گُل ہو جائیں گی اور سب اپنے اپنے گھروں کو لَوٹ جائیں گے۔
پیش منظر، پس منظر میں تبدیل ہو جائے گا اور نظامِ کائنات چلتا رہے گا۔
کیا شاہ رخ کو دیکھنا سہانہ کی کوئی آخری خواہش تھی؟
میرے دل میں اک ہوک سی اٹھی۔ اپنے ایکٹ کے دوران شاہ رُخ خاں نے مختلف لوگوں کو سٹیج پر بلایا اور اپنے ساتھ آئٹم میں شامل کر کے اُن سے باتیں کیں، اُن کے ساتھ ڈانس کیا۔
میرا شدت سے جی چاہا کہ کسی طرح شاہ رُخ خان کو ایک پرچی بھجواؤں جس پہ لکھا ہو کہ
تمہاری ایک مداح بسترِ مرگ سے اٹھ کر آج تمہیں دیکھنے، تمہارے فن کی پزیرائی کرنے کو یہاں چلی آئی ہے۔
اُس سے ذرا مل لو، اُس کے ساتھ بات کر لو، اُسے کوئی جھوٹی تسلی ہی دے دو۔
شاید اِس طرح اُس کی زندگی کے گنے چُنے لمحوں میں سے ایک آدھ لمحے کا ہی اضافہ ہو جائے۔
وقت کی پونجی سے جیب خالی ہو رَہی ہو، تو ایک لمحہ بھی ایک صدی کے برابر ہو سکتا ہے،
مگر مَیں اپنی اُس پاگل خواہش کو دل ہی دل میں دبائے بیٹھی رہی۔
اسٹیج پر کھڑے زندگی سے بھرپور دِلکش شخصیت والے شاہ رُخ خان تک یہ پیغام پہنچانا ناممکن تھا۔
لوگوں کی چیخیں، دیوانگی، تالیاں، سکیورٹی کے لیے لگائے گئے بڑے بڑے آہنی بیرئیر اور ہال کا نظم و نسق سنبھالنے والے موٹے موٹے بڑے ڈیل ڈول والے سیاہ سکیورٹی گارڈز۔
اُن سب کے ہوتے ہوئے ایک ننھی سی پرچی پہ لکھا ہوا کوئی پیغام اتنے بڑے فنکار تک کیسے پہنچایا جا سکتا تھا؟
کچھ ہی دیر میں منتظمین نے شاہ رُخ خان کو ایک لمبے سے پہیوں والے اسٹینڈ پر کھڑا کر کے حاضرین کے بالکل قریب سے گزرنے کا موقع دیا جس پہ لوگوں نے تالیاں پِیٹ پِیٹ کر خوشی کا اظہار کیا۔
سہانہ بھی کمزور ہاتھوں سے تالیاں بجا رہی تھی اور مسکرا رَہی تھی۔
شاہ رُخ لوگوں کے قریب آتا، ہاتھ ہلاتا، فلائنگ کس پھینکتا، پیار برساتا آہستہ آہستہ واپس چلا گیا۔
اُسے پتا بھی نہیں چلا کہ دو بجھے ہوئے دیوں میں کتنی خوبصورت جوت جل اٹھی ہے۔
اُسے تو بس یہ پتہ تھا کہ اُسے اپنے چاہنے والوں کو خوش کرنا ہے، اُن کا دل لبھانا ہے،
اِس لیے دوبارہ سٹیج پر نمودار ہوا اَور اَب کی بار اَپنے سب ساتھی فنکاروں کے ساتھ مل کر ڈانس کیے اور ڈائیلاگ بولے۔
اُس کے مزیدار چٹکلوں اور شوخ گفتگو سے ہال میں جوش کی سطح انتہا کو چھونے لگی۔
میرا جی چاہا گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخوں اور کہوں، شاہ رُخ اُس لڑکی کو مل لو ، وہ جا رہی ہے،
تمہیں وہ پھر کبھی نظر نہ آئے گی، کل وہ پتا نہیں ہو نہ ہو، مگر ایک ہیجانی شور میں میری آواز کیسے سنائی دے سکتی تھی۔
اِس لیے مَیں خاموش رہی۔
اسٹیج پہ زندگی تھرک رہی تھی۔ حاضرین کی رگوں میں بہنے والے خون کی قوت بڑھا رہی تھی ۔
موت ایک نشست پہ بیٹھی محظوظ ہوتی کسی کی ختم ہوتی سانسوں کی ریزگاری گن رہی تھی۔
’’ارے کوئی ہے جو شاہ رُخ کو جا کے بتائے؟‘‘
میرے دل نے ایک اور چیخ ماری اور مَیں پھر خاموشی سے شو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔
تین گھنٹوں بعد شو اختتام پذیر ہو گیا اور ہم سب ہال میں سے باہر نکلنے لگے۔
سہانہ کی بھابی نے اُسے تھام رکھا تھا کہ کہیں رش میں اُسے ٹھوکر نہ لگ جائے۔
’’برا حال ہے، چلا بھی نہیں جا رہا، لیکن کم از مَیں نے شو تو دیکھ لیا نا، کتنا مزہ آیا۔‘‘
سہانہ کی مردہ آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔
’’کئی بار پوچھا، چلنا ہے؟ مگر توبہ کریں جی یہ شاہ رُخ کو چھوڑ کر کہاں جانے والی تھی۔‘‘
سہانہ کی بھابی نے پیار سے اُس کے بازو کو تھپتھپایا، میری نم آنکھیں بھابی کی نم آنکھوں سے ٹکرائیں اور پھر نیچے جھک گئیں۔
یوں جیسے ہم اپنے زندہ ہونے اور باقی رہ جانے پہ شرمندہ اَور معذرت خواہ ہوں۔
آخر زندگی پر صرف ہمارا ہی حق کیوں تھا؟
سہانہ شاہ رُخ سے نہ مل سکی اور زندگی سہانہ کو، تو کیا ہوا۔
کسی تعلق کو قائم رکھنے یا ثابت کرنے کے لیے کیا کسی کا کسی سے ملنا ضروری ہوتا ہے؟
ایک ہی کہکشاں کے سیارے اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں،
ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہیں، مگر اُن کا ایک دوسرے سے تعلق تو پھر بھی ہوتا ہے۔
ہم سب کائنات کی گھمن گھیری کے ناچتے ہوئے بگولوں میں اڑتے ہوئے تنکے ہیں۔
آفاق کی اِس کارگہہ شیشہ گری کے بائیسکوپ میں جڑے شیشوں میں قید ہیں۔
یہ دنیا ایک تماشا گاہ ہے جہاں پردہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔
کردار انٹری دیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ شو کو تو چلتے رہنا ہے۔
جنم اور مرن کھلے سمندر میں تیرنے والی دو کشتیوں کا نام ہے۔
ہم خوشی مناتے ہیں جب جنم کشتی اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے۔
اِس سے بےنیاز کہ راستے میں اُسے کتنے طوفانوں، جھکڑوں، ہچکولوں کا سامنا کرنا ہو گا۔
ہم سوگ مناتے ہیں جب یہ کشتی کنارے جا لگتی ہے
حالانکہ ہمیں اُس وقت خوش ہونا چاہیے کہ کٹھن سفر ختم ہوا۔ مسافر نے منزل کو جا لیا اور اَب اُس کے نصیب میں آرام ہی آرام ہے۔
مَیں سہانہ کے لیے سوگوار نہیں ہوں۔ وہ پنہاں ہو گئی، تو کل یقیناً کسی لالہ و گُل میں نمایاں ہو جائے گی۔
باغِ حیات میں چلتی بادِ صبا مہکتی سرسراتی ہوئی جب کسی غنچۂ نَو کے رخسار پہ بوسہ دے گی،
تو شاید وہ بھی اِسی طرح پیار سے مغلوب ہو کر خوشی سے تالیاں بجائے گا
جیسے اُس روز سہانہ واشنگٹن ڈی سی کے ایم سی آئی ہال میں بجا رہی تھی۔
پھر بھی نہ جانے کیوں میری آنکھ کے کونے میں ایک اکیلا آنسو آتا ہے، تو آ کر اٹک سا جاتا ہے۔
دل میں یہ خیال اُبھرتا ہے کہ اگر کسی دن شاہ رُخ خان کو لالہ کے اُس پھول کے بارے میں پتا چل گیا،
تو اُسے کیسا لگے گا؟ کیا سوچے گا وہ اِس بےانت کہانی کے بارے میں؟