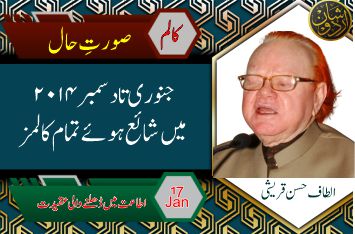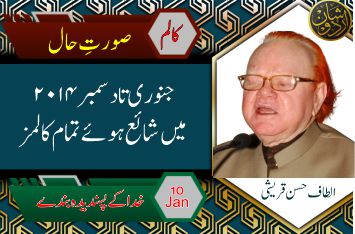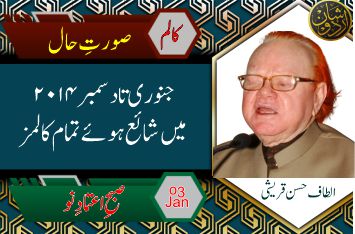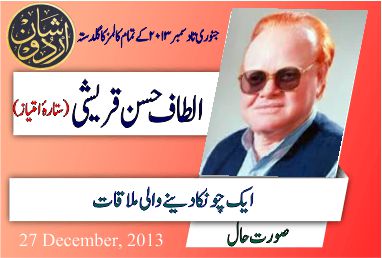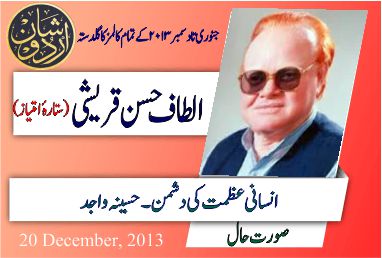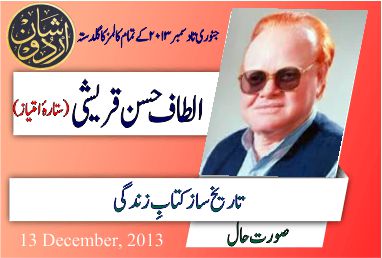افسانہ
نہ کسی کی آنکھ کا نور
نیلم احمد بشیر
’’السلام علیکم منے بھائی!‘‘ کوئی میرے پیچھے سے آ کر مجھ سے پُرجوش انداز میں بغل گیر ہو گیا۔
مَیں نے سر گھما کر دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اُس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میری گردن ہل ہی نہ پائی۔
کسی نے مجھے میرے بچپن کے نام سے پکارا۔
وُہ بھی یہاں امریکا کے اِس دور دَراز شہر بالٹی مور میری لینڈ میں؟ مَیں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کہ اُس نے اچانک اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔
مَیں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رَہ گیا کہ میرے سامنے میرے بچپن کا دوست صغیر کھڑا تھا۔
ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے تقریباً بیس سال ہو گئے تھے۔ پھر بھی اُس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اُس کے ساتھ اُس کی بیوی اور تین بچے بھی تھے۔
’’اوئے سگو! تُو یہاں کہاں؟‘‘ مَیں نے بھی اُسے لپٹاتے ہوئے مسرت سے کہا۔
اُسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں ہمارا کرشن نگر کی گلیوں میں بِتایا ہوا بچپن گھوم گیا۔
آوارہ گردیاں، محلے کی لڑکیوں سے عشق مشوقیاں، ہماری پتنگ بازی اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔
’’بس یار قسمت ہمیں بھی یہاں لے آئی اور کیا؟
پنچھیوں کا کیا ہے؟ جہاں دانہ پانی لکھا ہو، وہیں اُڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تُو سنا سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بال بچے کیسے ہیں، کہاں ہیں؟‘‘
وہ سوالات کرتا جا رہا تھا اور مَیں جلدی جلدی اُن کے جواب دے رہا تھا، کیونکہ شاپنگ مال کے باہر پارکنگ لاٹ میں میری بیوی ذکیہ اور بچے میرا اِنتظار کر رہے تھے ۔
اُن کے فون پہ فون آ رہے تھے کہ جلدی آئیں گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ مَیں نے اُسے اپنے گھر کا فون نمبر اور پتا بتایا اور اگلے ہفتے کے اختتام پر آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔
اُس سے مل کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اِس لیے وقت بمشکل ہی کٹا ۔ پھر ہفتے کے روز سگو اَور اُس کا کنبہ ہمارے ہاں دوپہر کے کھانے پہ چلے آئے۔
مَیں نے اپنے بچوں ندا اَور رَازی کا سگو سے تعارف کروایا، تو سگو نے بھی اپنے بچوں کو سامنے بلا کر سب سے ملوایا۔
’’یہ رضیہ ہے، یہ فرقان اور یہ ہمارا خاص بچہ شمس الرحمٰن!‘‘
مَیں نے صغیر کے وہیل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بارہ تیرہ برس کے بیٹے کو بغور دَیکھا، کتنا خوبصورت بچہ تھا وہ۔
یوں جیسے دنیا کی کسی آلودگی نے کبھی چھوا نہ ہو۔ جیسے وہ نیا نکور ہو اَور ابھی ابھی جنم لیا ہو۔ ایک اطمینان بھری پاکیزگی اُس کے چہرے پہ کِھلتی اور آنکھوں سے معصومیت چھلکتی تھی۔
’’کیا حال ہے بیٹے؟‘‘ مَیں نے شمس کو خاص طور پہ پیار کر کے اُس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔
’’بالکل ٹھیک جی!‘‘ وہ مسکرایا۔ مجھے اُس کا ٹھیٹھ پنجابی لاہوری لہجہ بڑا دِلچسپ لگا۔
’’یہ ہمارا فرشتہ ہے، ہمارا خاص بچہ۔‘‘ صغیر نے بھی اُسے ہولے سے تھپکتے ہوئے کہا اور ذکیہ کی طرف پیار سے دیکھا۔
ہم نے ایک دوسرے کے بچوں کو پیار کیا۔ نام پوچھے اور اُنھیں آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر ملتے جلتے دیکھ کر خود کھانے کی میز پہ آ بیٹھے۔ بچوں کو زبان کا مسئلہ درپیش آ رہا تھا۔
میرے بچے پیدائشی امریکن ہونے کی وجہ سے زیادہ تر انگریزی میں بات کرنے کے عادی تھے۔صغیر کے بچے نئے نئے پاکستان سے آنے کی وجہ سے صرف پنجابی ہی بول سکتے تھے۔
ہم اُنھیں زبانیں مکس کر کے بولتے دیکھ کر ہنسنے لگے اور اُنھیں اُن کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر کے آپس میں مصروف ہو گئے۔
’’یار سگو! تیرے آنے سے اپنا بچپن لَوٹ آیا ہے۔‘‘ مَیں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اُسے کہا۔
اُس نے بھی محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم لوگ گھنٹوں، گزرے دنوں کے قصے کہانیاں کہتے سنتے رہے۔
ہم دونوں کی بیویاں ہماری حماقتیں سن کر ہنستی رہیں ۔ ہمارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے، اچھلتے کودتے دوست بن گئے۔
’’ہاں یار! یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ تم لوگ آئے کب؟‘‘ مَیں نے صغیر سے پوچھا۔
’’اب تو تقریباً چھے ماہ ہو گئے ہیں۔ تھوڑا بہت گھر سیٹ کر لیا ہے۔ بچے اسکولوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ شمس الرحمٰن کا اسپیشل سکول میں داخلہ ہو گیا ہے۔
بس ابھی اِن کی انگریزی کمزور ہے، اِس لیے تھوڑا بہت مسئلہ ہے۔ پھر بھی یار اَللہ کا بہت شکر ہے۔‘‘ صغیر ایک ذمےدار متفکر باپ کی طرح بولا۔
ہم لوگ آئندہ جلد ملنے کا پروگرام بنا کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔
تقریباً ڈیڑھ دو ماہ بعد ایک روز صغیر نے مجھے فون کر کے خاص طور پر اپنے گھر آنے کو کہا۔ مَیں کام کے بعد سیدھا وہیں چلا گیا۔ بیوی کو فون کر دیا کہ رات کے کھانے پر میرا اِنتظار نہ کریں۔
صغیر کے گھر گھستے ہی مجھے چاروں طرف بندھا ہوا سامان، سوٹ کیس اور پیک شدہ ڈبے نظر آئے۔ مَیں نے حیران ہو کر اُس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟
’’کیا آپ لوگ کہیں اور منتقل ہو رہے ہیں؟‘‘
’’جی ہاں بھائی جان!‘‘ اُس کی بیوی ثمینہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔
’’کہاں؟‘‘ مَیں نے پوچھا۔
’’پاکستان!‘‘ صغیر نے مختصر جواب دیا۔
’’اچھا، مگر کیوں؟ میرا تو خیال تھا آپ لوگ اب یہیں رہیں گے۔‘‘
’’یار تجھ سے کیا چھپانا، ہم لوگ تو یہاں شمس الرحمٰن کے لیے آئے تھے۔
تجھے تو پتا ہے معذور بچہ کتنی بڑی ذمےداری ہوتا ہے۔ ہماری زندگی اُس کی وجہ سے بڑی الجھنوں کا شکار تھی۔ ہم نے سوچا امریکا جا کر اُسے کہیں داخل کروا دَیتے ہیں۔
تجھے تو پتا ہے یہاں کے کتنے سسٹم ہیں۔ پاکستان میں تو اُس کی معذوری کی وجہ سے ہم بڑے پھنس گئے تھے۔‘‘
’’مَیں کچھ سمجھا نہیں۔‘‘ مَیں نے جواب دیا۔
’’بھائی صاحب! ہمارے شمس الرحمٰن کو معذور ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ آف میری لینڈ نے اپنی ذمےداری بنا لیا ہے۔ اُسے یہاں ایک انسٹی ٹیوٹ میں رہائش، علاج، تعلیم سب کچھ ملے گا۔ وُہ بھی سرکاری خرچ پر، ہے نا خوش قسمتی کی بات؟‘‘ اُس کی بیوی ثمینہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔
’’بس ہم لوگ چند ہی روز میں پاکستان چلے جائیں گے۔ یار اَپنے نارمل بچوں کو سنبھالیں۔ اُن بےچاروں کو تو شمس الرحمٰن کی وجہ سے ہم لوگ پوری توجہ ہی نہیں دے پاتے تھے۔ اپنا کاروبار ہے وہاں، بس اب جانا ہو گا۔‘‘
’’ہمیں کیا ضرورت ہے کافروں کے ملک میں رہنے کی۔‘‘ ثمینہ نے تنک کر کہا۔
’’بس ہمارا بچہ ٹھیک جگہ پہنچ گیا۔ اب ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ اُس کا نگہبان ہو۔ سوہنے رب نے اُس کے لیے خود ہی سوہنا انتظام کر دیا ہے۔‘‘ ثمینہ نے تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔
اُسی لمحے نہ جانے کہاں سے چرچراہٹ کی آواز آئی۔ مَیں نے پلٹ کر دیکھا، شمس الرحمٰن غصّے بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اُس نے چلّانا شروع کر دیا:
’’انکل، انکل! مَیں ایتھے کلے نئیں رہنا۔ امی ابو مینوں چھڈ کے پاکستان چلے نیں۔ مَیں ایتھے نئیں رہنا۔ مینوں وی نال لے جاؤ۔‘‘
(انکل، انکل! مَیں نے یہاں اکیلے نہیں رہنا۔ امی ابو مجھے چھوڑ کر پاکستان جا رہے ہیں۔ مَیں نے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔)
بچے کی حالت دیکھ کر میرے ماتھے پہ بھی بل آ گئے۔
’’یار صغیر! بچہ یہاں نہیں رہنا چاہتا، تو تم اُسے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یار۔‘‘
’’میری بات سن منے بھائی! دیکھو ہم اِسے سمجھا رہے ہیں کہ اِس کی خاص دیکھ بھال، میڈیکل چیک اپ، اسکولنگ، رہائش سب کچھ بہترین ہو گی۔
یہ تو خوش قسمت ہے۔ پاکستان میں اِس کی کوئی زندگی، کوئی مستقبل نہیں۔ یہاں تو معذور اَفراد بھی معاشرے کا اہم حصّہ سمجھے جاتے ہیں۔
نہ بھئی۔ اِس کے لیے بہتر ہے کہ یہیں رہے۔ اِس بےوقوف کو نہیں پتا کہ اِس کی تو زندگی بن جائے گی۔ ویسے بھی ہم سب کا سیاحتی ویزا ختم ہونے والا ہے۔
ہم لوگ اب یہاں رہ ہی نہیں سکتے، تو مجبوری ہے نا۔‘‘ صغیر نے وضاحت کی۔
صغیر اور اُس کی بیوی نے مجھے اور ذکیہ کو اَگلے روز خاص طور پر اپنے گھر آنے کی تاکید کی تاکہ ہم سب مل کر شمس الرحمٰن کو اُس کے نئے گھر ہاسٹل پہنچا آئیں۔
ہم سب لوگ دن کے تقریباً بارہ بجے انسٹی ٹیوٹ پہنچ گئے اور اِنتظارگاہ میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔
’’دیکھا کتنی سہولتیں ہیں یہاں۔‘‘ صغیر مستعد عملے کو اِدھر سے اُدھر جاتا، صاف ستھرے ماحول میں کام کرتا دیکھ کر خوشی سے کہنے لگا۔
’’اللہ کرے میرے پتر کا اچھی طرح خیال کریں یہ لوگ۔‘‘ شمس الرحمٰن کی ماں کے چہرے پہ اداسی کی ایک سانولی سی پرچھائیں نظر آئی۔ مگر پھر جلد ہی غائب ہو گئی۔
’’او ثمینہ! تُو فکر نہ کر۔ اِن گوروں کے پاس بہت پیسہ ہے اور روپیہ ہو تو زندگی کی ہر سہولت خریدی جا سکتی ہے۔
اِنھیں کون سی تنگی ہے کہ وہ اَپنے ہاں داخل ہونے والے بچوں کا خیال نہ رکھیں۔ یہ کوئی پاکستان تھوڑا ہے۔‘‘
صغیر نے اُسے تسلی دی، تو ثمینہ مطمئن ہو کر شمس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی جو ایک خوف زدہ بلونگڑے کی طرح اِدھر سے اُدھر دیکھ کر ہولے ہولے سسکیاں لے رہا تھا۔
ثمینہ نے آیت الکرسی والا تعویذ اُس کے گلے میں ڈال دیا اور دُعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکیں مارنے لگی۔
’’بس میرا پتر! حوصلے نال رہنا اے تُوں۔‘‘ (بس میرے بیٹے! تم نے حوصلے کے ساتھ رہنا ہے۔)
ماں نے پچکارا، تو بیٹا زور زور سے رونے لگا۔
’’کیا ملک ہے یار! ہر چیز اتنے قاعدے، سسٹم سے ہوتی ہے کہ بس۔‘‘ صغیر نے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تبصرہ کیا۔
’’ابا! مینوں چھڈ کے نہ جا۔ مَیں ایتھے نئیں رہنا۔‘‘
(ابا! مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ مَیں نے یہاں نہیں رہنا۔)
شمس نے وہیل چیئر کو زور زور سے ہلا کر بلکنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو نرسیں دوڑی آئیں اور آ کر اُسے انگریزی میں پیار سے پچکار کر کہنے لگیں:
’’سویٹ ہارٹ! گھبراؤ نہیں۔ یہ تمہارا اَپنا گھر ہے۔ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو گی۔ تمہارے جیسے اور بھی بچے ہیں۔ اُن سے دوستی ہو جائے گی، تو تم بڑا لطف اٹھاؤ گے۔‘‘
نرس نے دوسرے مکین بچوں کی طرف سے شمس کے لیے بنائے گئے استقبالیہ کارڈز اور ننھے ننھے تحائف کے ڈبے شمس کی گود میں لا کر رکھ دیے، مگر اُسے اُس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
نہ ہی اُسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اُس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ نرسوں کے امریکن لب و لہجے میں بولی جانے والی انگریزی اُس کے بالکل بھی پلے نہیں پڑ رہی تھی۔
اُس کے چیخنے چلّانے سے پریشان ہو کر ایک اور نئے داخل ہونے والے بچے نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ یہ بچہ شمس کے برعکس ذہنی طور پر معذور تھا۔
اُس کی ناک سے بہتا پانی اور رَال اُس کا چہرہ خراب کرنے لگے، تو نرس نے مادرانہ شفقت سے اُس کا چہرہ ٹشو سے صاف کیا اور اُسے بازوؤں میں بھر کر پچ پچ کرنے لگی۔
’’دیکھیا کنی اچھی طرح اے نویاں مانواں تیرا خیال رکھن گیاں۔‘‘ (دیکھا، کتنی اچھی طرح یہ نئی مائیں تمہارا خیال رکھیں گی)
شمس کی ماں نے بیٹے کو تسلی دینے کی کوشش کی۔
وقتِ رخصت قریب تھا۔ ہم سب نے اُسے باری باری پیار کیا اور وَقت ختم ہونے پر وہاں سے چلنے لگے۔
شمس کے پھیلے ہوئے بازو اَور دِلدوز چیخوں نے طبیعت بوجھل اور مکدر کر دی تھی، اِس لیے ہم سب خاموشی سے وہاں سے لَوٹ آئے۔
ایک دوسرے سے یوں نظریں چرا رَہے تھے جیسے سبھی مجرم اور گنہگار ہوں۔
چند دنوں بعد صغیر اپنے بال بچوں کو لے کر پاکستان واپس چلا گیا اور پھر مجھے مدتوں اُس کی کوئی خیر خبر نہ ملی۔
مَیں اور میری بیوی کئی بار شمس کو یاد کرتے اور اُس کی باتیں کرتے۔ کبھی جی چاہتا، اُسے جا کر دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے، مگر سچی بات ہے ہمارا حوصلہ ہی نہ پڑتا اور نہ کبھی وقت ملتا۔
بس ہم ٹال مٹول کر رہ جاتے۔ پھر یہ بھی خیال آتا کہیں وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھ جانے کی ضد ہی نہ کر دے۔ ایسا ہوا، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟
ظاہر ہے ہم کسی کا بچہ اپنے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اتنا بڑا دِل یا گھر تو ہمارا بھی نہیں تھا۔
ویسے بھی وہ ہماری نہیں اپنے ماں باپ کی ذمےداری تھا۔
اُنھی کا فرض اور حق بنتا تھا کہ وہ اُسے سنبھالیں، پالیں، جیسے چاہے رکھیں یا پھینک دیں۔
اور پھر اچانک ایک روز ہمیں کہیں سے صغیر کا ٹیلی فون آ گیا۔
وہ پھر ہمارے شہر میں آیا ہوا تھا اور ہم سے ملنے کی خواہش کر رہا تھا۔
ہم تو اُسے اور اُس کے کنبے کو تقریباً بھول ہی چکے تھے، مگر اُس کے فون نے پھر سے شمس الرحمٰن کی یاد تازہ کر دی۔
’’سب ٹھیک تو ہے نا؟‘‘ مَیں نے اُس سے بڑا سرسری مگر گہرا سوال کیا۔
’’ہاں اللہ کا شکر ہے، بس یار مل کر بتاؤں گا۔‘‘ اُس نے جواب دیا ۔
مَیں نے اگلے ہفتے کے اختتام پر اُسے گھر آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔
یہ فروری کی اُکتا دینے والی سردی کے ٹھنڈے اداس اور منجمد دن تھے۔ برف کے طوفان تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔
درخت سفید لبادے اوڑھے ہونقوں کی طرح خاموش کھڑے تھے۔
بہار دُور تھی اور دِل منتظر کہ کب شگوفے کھلنے کا موسم آئے اور مسکراہٹیں لبوں پہ کِھلنے کا اذن مانگیں۔
صغیر اکیلا ہی آیا۔ ہم نے اُس کی بیوی بچوں کے بارے میں استفسار کیا، تو اُس نے بتایا کہ وہ لاہور ہی میں ہیں۔ ساتھ نہیں آئے۔
’’یار کتنا وقت گزر گیا تجھے ملے ہوئے اور اَب تو ہم لوگ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔‘‘ اُس نے میرے گنجے ہوتے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
مَیں مسکرا دِیا اور جواباً اُس کی بڑھتی ہوئی توند کی طرف انگلی کر کے اُس کی بات کی تائید کی۔
’’اور سناؤ، اتنے برسوں بعد کیسے دوبارہ اَمریکا آنا ہوا؟‘‘ مَیں نے کھانے کے دوران لقمہ توڑتے ہوئے پوچھا۔
’’بس یار کوشش تو پچھلے کئی برسوں سے کر رہا تھا، مگر بیچ میں کم بخت نائن الیون جان کو آ گیا ۔ گورے چالاک ہو گئے۔ ویزا ہی نہیں دیتے اب۔
پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی ہے، ڈکیتیاں ہیں اور میرا کاروبار بھی بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ روزگار سے تو جیسے برکت ہی اُٹھ گئی ہے۔
آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اچھے وقتوں میں امریکا سیٹل ہو گئے۔ اب تو یہاں کی امیگریشن بس ایک خواب بن کے رہ گئی ہے۔‘‘ اُس نے حسرت سے ٹھنڈی آہ بھری۔
’’پھر بھی بھائی صاحب! آپ کو سیاحتی ویزا تو مل ہی گیا نا، شکر کریں۔
اب تو وہ بھی ملنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ زمانے گئے جب یہ سب آسان تھا اور آپ نے شمس بیٹے کو آرام سے یہاں جمع کروا دِیا تھا۔‘‘ میری بیوی کے لہجے کی ناگواری چھپی نہ رہ سکی تھی۔
’’شمس کیسا ہے، کہاں ہے؟‘‘ منہ آئی بات نہ رہ سکی اور مَیں نے سوال کر دیا۔
’’یہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ پڑھائی میں بہت اچھا جا رہا ہے۔
اُس کی رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں سکول والے۔ دراصل عنقریب اُس کی ہائی اسکول گریجوایشن ہے۔ اُس کے بعد وہ کالج میں داخل ہو جائے گا۔ شکر ہے، اُس کی تو زندگی بن گئی۔‘‘ وہ بولتا چلا گیا۔
’’تو آپ اُس کی گریجوایشن پہ آئے ہیں؟‘‘ میری بیوی طنزیہ انداز میں بولی۔
’’جی بھابی جی! آخر اتنا اہم وقت ہے اُس کے لیے۔ ایسے میں کم از کم اُس کے والدین میں سے کسی ایک کو تو ہونا چاہیے نا۔‘‘ وہ ایک ذمےدار باپ کی طرح بولا۔
’’یار! مَیں نے کہنا تھا کہ مَیں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں ہوں۔ اُس کی ہائی اسکول گریجوایشن کے موقع پہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں، تو مجھے اور شمس کو بہت اچھا لگے گا۔
دراصل مَیں اُسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اُسے یہ بالکل پتا نہیں کہ مَیں یہاں آیا ہوا ہوں۔
کتنا خوش ہو گا وہ مجھے اور پھر آپ سب کو دیکھ کر بھی۔ آخر یہاں تو آپ لوگ ہی ہمارے اپنے ہیں۔‘‘
’’پانچ سال سے آپ نے اُسے دیکھا نہیں، پہچان بھی لیں گے اُسے یا نہیں؟‘‘
’’لو کمال کرتی ہیں بھابی جی! اپنا خون ہے، کیسے نہیں پہچانوں گا؟ بس مَیں تو تصوّر میں ہی اُسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں کہ کتنا بڑا ہو گیا ہو گا۔‘‘
اُس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، تو میری آنکھیں بھی نم سی ہو گئیں۔
یہ والدین اور اَولاد کا رشتہ بھی کتنا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ ایک ڈور سی ہوتی ہے جو بس بندھی رہتی ہے۔
تعلق ہوتا ہے جو کبھی مٹتا نہیں، جنون ہوتا ہے جو کبھی گھٹتا نہیں۔
گریجوایشن ڈے پہ مَیں، میری بیوی اور صغیر مقررہ وَقت پہ اسکول کے ہال میں جا پہنچے۔ ہمیں خصوصی مہمانوں کی آگے والی نشستیں ملیں جہاں سے سٹیج کا منظر بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔
اسکول کا عملہ صاف ستھرے یونیفارم پہنے، خوش باش، مستعدی سے اپنا کام نمٹاتا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ والی نشست پر بیٹھ کر صغیر مجھ سے شمس الرحمٰن کی پرانی باتیں کرنے لگا۔
اُس نے بتایا کہ اُس کی ٹانگوں کی کمزوری کسی پٹھوں کی بیماری کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ بچپن میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک اُسے اِس مرض نے آن لیا ۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب کبھی دوبارہ نارمل طریقے سے چل پھر نہیں سکے گا۔
’’مگر یار ذہن اُس کا غیرمعمولی طور پہ بہت تیز تھا۔ ہمیشہ جماعت میں اوّل آتا اور اِنعام جیتا کرتا تھا۔
اب تو اللہ کے کرم سے وہ دُنیا کے بہترین ملک کے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اب تو ماشاء اللہ اور بھی لائق فائق ہو گیا ہے۔‘‘
’’آپ اُسے فون نہیں کرتے تھے؟ میرا مطلب ہے، اُس کے اسکول کی پراگریس رپورٹ لینے کے لیے؟‘‘ میری بیوی پوچھنے لگی۔
’’نہیں بھابی جی۔ کلیجے کا ٹکڑا ہے نا۔ بس حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا۔ کیا پوچھتے اُس سے؟ اگر وُہ رَو دَیتا، تو ہم لوگ وہاں سکون سے نہیں رہ سکتے تھے۔‘‘ صغیر نے متفکرانہ انداز میں جواب دیا۔
’’اسکول والوں نے تقریب کا دعوت نامہ بھیجنے کے ساتھ ایک خط بھی نتھی کیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم ہر گریجوایٹ کو اَپنے ایک پروگرام Heart’s Desire (دل کی خواہش) کے تحت ایک خواہش پوری کرنے کا موقع دیتے ہیں۔
یہی اُن کا گریجوایشن کا تحفہ ہوتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، خواہشِ دل۔‘‘ صغیر نے ہماری طرف دیکھ کر تائید چاہی۔
’’ہاں واقعی خواہشِ دل تو بہت خوبصورت بات ہے۔‘‘ مَیں نے بھی سر ہلا دیا۔
’’مَیں نے سوچ لیا ہے۔ شمس کو ملتے ہی کہوں گا ’پتر! اپنی پوری فیملی کے لیے یہاں کی امیگریشن مانگ لے۔‘
بس پھر تو سارے کے سارے ہی یہاں آ جائیں گے۔ خیری سلا۔ کنبہ اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ وقت ہے کہ تُو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر کے دکھائے۔‘‘ صغیر کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔
فنکشن کا آغاز بہت خوبصورت اور باوقار اَنداز میں ہوا۔ طلبہ نے مل کر عالمی امن کی خواہش کے حوالے سے ایک مسحور کُن گیت پیش کیا۔
ہم نے وہیل چیئرز پہ بیٹھے بچوں میں سے شمس کو پہچاننے کی کوشش کی اور پھر بالآخر صغیر کی نشان دہی پر ایک کو بغور دَیکھنا شروع کر دیا۔
وہ وَاقعی شمس الرحمٰن تھا، مگر پہلے سے کتنا لمبا اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ سبھی بچوں میں گریجوایشن کے ڈپلومے تقسیم کیے گئے، تالیاں بجیں اور غبارے ہوا میں چھوڑے گئے۔ کامیابی اور محبت کے نغمے گائے گئے۔
’’میرا سوہنا پتر!‘‘ صغیر نے زیرِ لب کہا اور دِل کھول کر تالیاں بجائیں۔
تقریب کے بعد ہم تینوں شمس سے ملنے ہاسٹل کے بڑے سے میٹنگ ہال میں پہنچ گئے جہاں بچوں کے ماں باپ، رشتےدار، اُن سے ملاقات کے لیے کرسیوں پر پہلے ہی براجمان تھے۔
اُن کے مشتاق دل اور متلاشی آنکھیں اپنے پیاروںکو ڈھونڈنے کے لیے اِدھر اُدھر دیکھتی چلی جا رہی تھیں۔
ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے وائلن بجانے والے میٹھی میٹھی دھنیں بجا رہے تھے ۔کھڑکیوں کے شیشوں سے برف کے سفید سفید پھول ٹکڑا ٹکڑا کر تاک جھانک کر رہے تھے۔
’’یہ دیکھو ینگ مین! تمہیں ملنے کون آیا ہے؟‘‘ ایک اٹینڈنٹ نے آگے بڑھ کر شمس کو متوجہ کیا جو مزے سے چاکلیٹ کھاتا اُن کے پاس سے گزر رَہا تھا۔
صغیر آگے بڑھا اور جا کر شمس سے لپٹ گیا۔ ’’میرا پتر، میرا سوہنا پتر۔‘‘ وہ اُس کے ماتھے پہ بوسے دینے لگا۔ شمس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور ایک دم بولا:
’’معاف کیجیے گا۔ پیچھے ہٹیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟‘‘ اپنے بیٹے کے منہ سے شدھ امریکن لب و لہجے میں انگریزی سن کر صغیر مسکرا کر ہم سے مخاطب ہوا۔
’’کتنی اچھی انگریزی بولنے لگا ہے میرا پتر۔ او پتر پہچانا نہیں، مَیں تیرا اَبا۔‘‘ صغیر نے پھر اُس سے لپٹنے کی کوشش کی۔ شمس نے اُسے دھیرے سے پرے ہٹا دیا۔
’’آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ نرس! یہ کس زبان میں بات کر رہے ہیں۔
I don’t understand this language.
(مَیں یہ زبان نہیں سمجھتا۔)
اُس نے انگریزی میں بات کا جواب دیتے ہوئے کندھے اچکائے۔
’’اوئے یو آر شمس الرحمٰن، ڈونٹ فارگیٹ۔‘‘ اب کے صغیر بھی ذرا سخت لہجے میں بولا۔
’’لو جی یہ تو اپنی زبان ہی بھول گیا ہے۔‘‘ وہ بڑبڑایا۔
’’معذرت چاہتا ہوں! مَیں آپ کو نہیں جانتا۔ میرا نام شمس نہیں Shamus Raymond (شے مس ریمنڈ) ہے۔‘‘
اُس نے چبا چبا کر اپنا نام بتایا اور ہمارے حیرت سے کھلے کے کھلے منہ دیکھ کر چہرہ پرے کر لیا۔
اُسی لمحے اعلان ہونے لگا۔ ’’طلبہ اپنی اپنی دل کی خواہش بتائیں، ہم اُسے پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔‘‘
چند بچوں کے بعد ہی شمس الرحمٰن کی باری آ گئی۔
اُس نے مائیک ہاتھ میں تھام کر پہلے ایک اسٹاف ممبر کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہنے لگاـ:
’’میرے دل کی خواہش ہے کہ مَیں اُس شخص یا اُس کی فیملی کو آئندہ زندگی میں پھر کبھی نہ دیکھوں۔
مَیں امریکن ہوں اور یہ خواہ مخواہ ہی مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہ رَہے ہیں جبکہ مَیں اِنھیں جانتا تک نہیں۔
Please keep them away from me. (برائے مہربانی اِنھیں مجھ سے دور رَکھیں۔)
یہی میری خواہش ہے۔‘‘
’’خون سفید ہو گیا ہے بےحس لڑکے کا۔ دیکھو تو سہی۔‘‘
بالکل ہی امریکن ہو گیا ہے۔ صغیر نے غم و غصّے سے بڑبڑانا شروع کر دیا۔
شمس رے منڈ اَپنی موٹرائزڈ، جدید ترین سہولتوں سے مزین وہیل چیئر کو مشاقی سے چلاتا ہوا کاریڈور میں سے دُور تک جاتا دکھائی دیتا رہا اور باہر برف گرتی رہی۔