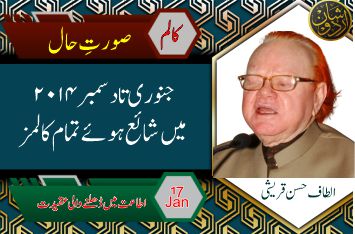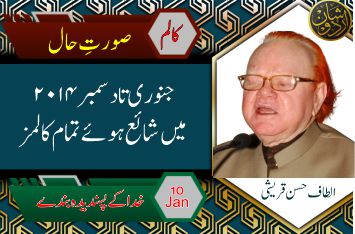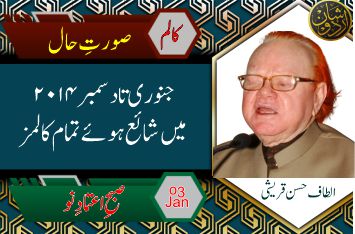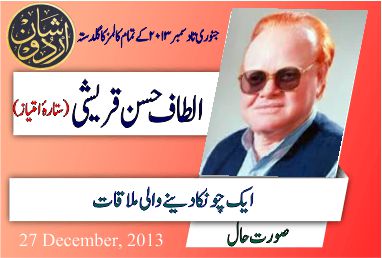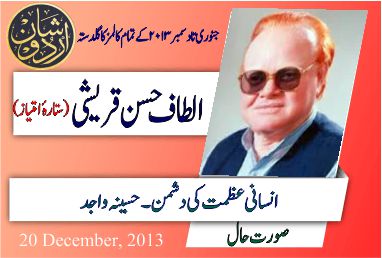افسانہ
بِس کا پیالہ
نیلم احمد بشیر
’’مسئلہ کیا ہے؟ ابھی تو تیرے سنڈے فیچر کے آنے میں کافی وقت پڑا ہے، تو پھر پریشانی کیسی؟‘‘ ندیم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے دوست اسد سے پوچھا۔
’’کچھ نہیں یار! موضوع ذرا مشکل سا ہے۔ ملازمت پیشہ عورتوں کے ہاسٹل کے مسائل اور اَبھی کوئی خاص انٹرویوز اور معلومات اکٹھی نہیں ہو سکیں۔‘‘ اسد نے متفکرانہ انداز میں جواب دیا۔
’’کیا، وہ ثمینہ گل تعاون نہیں کر رہی؟ پرانی رہائشی ہے اُس ہاسٹل کی۔ ویسے کرتی کیا ہے؟ وہ تو تیری کافی مدد کر سکتی ہے۔ اُس سے پوچھنا۔‘‘
’’وہ بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے کسی بڑے عہدے پہ۔ بڑی مصروف ہوتی ہے یار۔ اُسی سے تو وقت لینا مشکل ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی بہت دیر تک ڈیوٹی کرتی ہے۔ اُس سے بات کر رہا ہوں۔‘‘ اُس نے جواب دیا۔
’’ثمینہ ویسے ہے بڑی پُرکشش شخصیت والی۔ اُس روز دیکھا تھا اُسے۔ مَیں نے کہا، لو بھئی اپنا یار تو گیا۔‘‘ ندیم ہنسنے لگا۔
’’چل بکواس نہ کر۔ مگر یار ندیم پتا نہیں اُس لڑکی میں کیا بات ہے۔ ایک ہی بار ملا ہوں مگر اُس کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی گہری اداسی۔
بڑی عجیب سے کشش ہے، اُس کی آنکھوں میں۔‘‘ اسد بات کرتے کرتے کھو سا گیا۔
کچھ ہی دیر میں ورکنگ ویمن ہاسٹل کا گیٹ آ گیا۔ اَسد اتر کر چوکیدار سے اندر جانے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ چوکیدار نے مہمانوں کو انتظار گاہ میں بٹھا دیا ۔ خود ثمینہ گل کو بلانے کے لیے فون کرنے چلا گیا۔
ثمینہ نے اُس کے ساتھ ہاسٹل کے مسائل پر تفصیلاً بات چیت کی۔ اُس نے بتایا کہ خواتین کو ہاسٹل میں رہنے سے آرام تو ملتا ہے، مگر ساتھ ہی کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔
آنے جانے کا مسئلہ،
مشترکہ کمرے میں سیٹنگ کے انتظامات کی دشواری،
مہنگے بِل،
کھانے کا ناقص معیار وَغیرہ۔
سبھی موضوع زیرِبحث آئے۔
’’کہیں باہر چلیں؟ میرا مطلب ہے آپ کو کافی، چائے کچھ پلاتے ہیں، مزا رَہے گا۔‘‘
ندیم خشک قسم کے موضوعات سے بور ہونے کے بعد بولا۔ ثمینہ نے کچھ دیر کے لیے سوچا۔
ایک آدھ بہانہ بھی بنایا، مگر اسد کے اصرار پر ہاں کہہ کر اُن کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ تینوں ایک پُروقار سی کافی شاپ میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے، ہنستے ہنساتے رہے۔
ثمینہ کے کپڑوں، انگلیوں میں پہنی ہوئی ہیرے کی انگوٹھیوں اور خوبصورت درآمدشدہ جوتی کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اَپنے پارلر کی ملازمت سے اچھا خاصا کما لیتی ہے۔
’’اگر آپ کے اتنے مسائل ہیں، تو آپ ہاسٹل کے بجائے علیحدہ مکان میں کیوں نہیں رہتیں؟‘‘ ندیم نے اُس سے بےدھڑک سوال کر دیا۔ ’’میرا مطلب ہے آپ استطاعت تو رکھتی ہیں نا۔‘‘
’’دراصل میرے والد اور دو چھوٹے بھائی ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں۔ والدہ کا تو عرصہ ہوا اِنتقال ہو گیا۔
مجھے علیحدہ مکان لے کر کیا کرنا ہے؟
سکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بس گزارا ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔‘‘ ثمینہ نے جواب دے کر گفتگو کا رُخ اسد کی اخبار کی اُس اسائنمنٹ کی جانب موڑ دیا جس پہ وہ کام کر رہا تھا۔
گاؤں کے لوگ خوش تھے کہ اب کے برس سرکس بڑے اچھے موسم میں آیا تھا۔
بہار کی آمد آمد تھی۔ ہوا میں خنکی بھلی لگتی تھی اور شامیانے کے اندر حبس محسوس نہیں ہوتا تھا۔
گرمیوں میں سرکس آتا، تو تماشائیوں کا برا حال ہو جاتا۔ کچی زمین پہ بندھے ہوئے جانوروں کی پیشاب کی باس،
سرکس کے کارندوں کے نائیلون سے بنے چست ملبوسات سے اٹھتے ہوئے پسینے کے بھبکے
چہرے سے ٹکرانے والی گرم لُو کے تھپیڑے کسی کو بھی بھرپور پر لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں دیتے تھے۔
اب کی بار اَچھا تھا، سرکس اور میلہ خوشگوار موسم میں آئے تھے۔
دس سالہ منا اپنے یار بیلیوں کے ساتھ شام کو سرکس کا پہلا شو دیکھنے کے لیے دوپہر سے ہی تیار ہوا بیٹھا تھا۔ ابو پولیس کانسٹیبل اکرم الٰہی گاؤں کے ایک معتبر آدمی تھے۔
سرکس والوں نے پہلے سے ہی آٹھ دس مفت کے پاس بجھوا دِیے تھے۔ اس کی وجہ سے منے کا اپنے دوستوں میں بڑا ٹہکا بن گیا تھا۔ وہ کلف لگے، اکڑے ہوئے شلوار کرتے میں ملبوس کب سے منتظر تھا کہ شام ہو اَور وُہ اپنے دوستوں کے ساتھ سرکس کے گول خیمے میں شان سے داخل ہو سکے۔
اسد نے ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل والا فیچر اپنے ایڈیٹر گیلانی صاحب کو دے دیا۔
وُہ چھپ بھی گیا، مگر نہ جانے کیوں ثمینہ گل اُس کے ذہن پر چھا کر رہ گئی۔
اُسے بھولتی ہی نہ تھی۔ ہر وقت اُس کا خیال آتا اور دِل بےچَین سا ہو جاتا۔
اُس لڑکی سے ابتدائی ملاقاتوں کو آخری سمجھنے پر دل رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ اُس عام سی شکل و صورت والی سانولی سلونی لڑکی کا بات بات پر چونک جانا،
اپنے گھنگھریالے بالوں کے چھلوں کو انگلی سے مستقلاً مروڑتے رہنا،
کبھی اُس کی طرف بھرپور انداز میں دیکھنا۔
کبھی اُس کی موجودگی سے بےخبر اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہنا، اسد کو تنہائی میں رہ رَہ کر یاد آنے لگا۔
وہ اَپنے آپ سے جنگ کرنے لگا،
’’اُسے فون کروں یا نہ کروں؟ کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں؟ کہیں کوئی غلط رائے ہی نہ قائم کر لے؟‘‘
آخر ایک روز تنگ آ کر اُس نے اُسے فون کر دیا ۔
پھر فون پہ گفتگو کا سلسلہ قائم کرنے کے بعد ایک روز اُسے باہر کھانے پہ مدعو کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔
اُس نے لاکھ مصروفیت کا بہانہ بنایا، مگر اسد نے اُس کی ایک نہ چلنے دی۔
’’تمہارے گھر والے تو تم پہ بہت مان کرتے ہوں گے۔‘‘ وہ کھانے کے دوران کہنے لگا۔
’’پتا نہیں، شاید!‘‘ وہ دِھیرے سے مسکرائی۔
’’بھئی تم اُن کے اتنا اچھا بیٹا ہو۔ اُنھیں سپورٹ کرتی ہو، محنت کرتی ہو۔‘‘
’’بیٹا!‘‘ وہ ہنس پڑی۔ ’’اچھا لگا تمہارا بیٹا کہنا۔‘‘
ہنستے ہنستے آئس کریم اسد کے بازو پہ ٹپکا دی۔ اسد نے فوراً آستین الٹ کر ٹشو سے آئس کریم صاف کر دی۔
ثمینہ غور سے اُس کا بازو دَیکھنے لگی۔
’’لگتا ہے میرے قوی۔ خوبصورت بازو کو دیکھ کر تمہارے دل میں کچھ کچھ ہونے لگا ہے۔‘‘
وہ اَپنے بالوں سے بھرے خوبصورت بازو سے قمیص اُٹھا کر اُسے دکھا کر اترانے لگا، تو ثمینہ ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی۔
’’ہنستی رہا کرو، ہنستی ہو، تو بڑی اچھی لگتی ہو۔‘‘ اسد کہنے لگا۔
’’زندگی اِسی کا نام ہے۔‘‘
’’اچھا! تم زندگی کو سمجھتے کیا ہو آخر؟‘‘ ثمینہ نے اچانک سوال کر دیا۔
’’مَیں سمجھتا ہوں زندگی ایک جام ہے۔ فرحت بخش، خوش رنگ اور خوش ذائقہ۔ تم زندگی کو کیا سمجھتی ہو؟‘‘
اسد نے جواباً اُس سے سوال کر دیا۔ ثمینہ خاموش ہو کر خلا میں گھورنے لگی۔
سرکس میں ہر طرح کے تماشے تھے۔ ہاتھی کا اسٹول پہ چڑھ کر سونڈ اُٹھا کر چیخنا،
ننھے ننھے سفید کتوں کا جلتی آگ کے پہیے میں سے بحفاظت کود جانا،
مسخروں کی الٹی سیدھی چھلانگیں،
تنے ہوئے رسے پہ جوان لڑکے، لڑکیوں کا توازن قائم رکھتے ہوئے مشاقی سے جھولے لینا،
شیروں کا دہاڑنا۔
منے اور اُس کے دوستوں کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
پھر پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک ایسا انوکھا تماشا دکھایا گیا جو کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا تھا۔
تماشے میں سب سے پہلے بتیاں مدھم کر دی گئیں جس سے ماحول کافی پُراسرار سا ہو گیا۔ لوگ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔
بڑی سی چھت والے گول سفید رنگ کے شامیانے کے عین بیچوں بیچ ایک میز لا کر رکھی گئی۔ اس پہ ڈھکی چادر کے نیچے کوئی لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔
ڈھول کی تھاپ دھیمی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی نے دھیرے دھیرے کپڑا سرکایا، تو حاضرین کے سانس اُوپر کے اُوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔
کانچ کے رنگ برنگے ٹکڑوں کی کئی تہوں کے اُوپر ایک نو دس برس کی لڑکی نیم عریاں لباس پہنے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔
یوں جیسے وہ ایک بےجان گڑیا ہو۔ تماشا گر نے مائیک تھام کر اعلان کیا:
’’بھائیو اور بہنو! آج نظارہ کیجیے میری بچی کی بہادری کا۔ ایسا تماشا آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو گا۔‘‘
پھر اُس نے اپنے ایک ہاتھ کو بلند کیا۔
اُس میں تھامی گول سی ٹوکری کا ڈھکنا بیٹی کے بالکل قریب لا کر دھیرے دھیرے کھولنا شروع کر دیا۔
ڈھول کی تھاپ تیز ہونے لگی۔
مسخرے دیوانے ہو کر ناچنے لگے۔ حاضرین کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ موسیقی کا شور بڑھ گیا۔
’’چلو! کسی دن اسلام آباد چلتے ہیں۔‘‘ اسد نے ثمینہ سے کہا۔
’’کیوں؟‘‘
’’امی ابو سے ملتے ہیں۔ گپ لڑائیں گے۔ امی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے۔‘‘
اسد نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران اچانک پیش کش کی اور ثمینہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔
ثمینہ باتیں کرتے کرتے یک دم خاموش ہو گئی۔ یوں جیسے اچانک کمرے کی بجلی چلی گئی ہو۔
پل بھر توقف کرنے کے بعد بولی۔
’’اسد ہم لوگ تو گلوبل وارمنگ کے مسئلے پر بات کر رہے تھے، یہ اچانک امی ابو کا ذکر کہاں سے آ گیا؟‘‘
’’بھئی مَیں نے سوچا گلوبل وارمنگ کے بعد اب ذرا دِلی جذبات کی بات کر لیں، تو کیا بولتی ہو؟ آتی کیا اسلام آباد؟‘‘ وہ لہک لہک کر گانے لگا۔
’’سوری اسد! تم جانتے ہو کہ مَیں بہت مصروف ہوتی ہوں، کہاں وقت ملے گا مجھے۔‘‘
’’دیکھو مَیں آخر کسی خاص وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں نا، چلو ۔ پلیز۔‘‘
’’اسد! میرا خیال ہے مَیں ایک بات واضح کر دوں، تو اچھا ہے۔
مَیں مستقبل کے کسی ارادے میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی۔ کیا ہم صرف اچھے دوستوں کی طرح نہیں مل سکتے۔
تمہیں شاید پتا نہیں مجھے ایک اچھے، پُرخلوص دوست کی کتنی شدید ضرورت ہے۔‘‘ اُس کی آواز بھرانے لگی۔
’’پاگل لڑکی! اگر دوست ایک دوسرے کے ساتھی بھی بن جائیں۔ ہمیشہ ساتھ نبھائیں، تو اِس میں کیا برا ہے۔
تم تقریباً چھے ماہ سے مجھے دیکھ رہی ہو۔ مَیں شریف لڑکا ہوں۔
سگریٹ پیتا ہوں نہ شراب۔ ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے، تم چاہو تو اَپنی ملازمت جاری رکھ سکتی ہو، ہم مل جل کر۔‘‘
’’اسد پلیز! مجھے ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا۔
آج کے بعد یہ بات نہ ہی چھیڑو، تو بہتر ہے۔ ورنہ مَیں تمہیں ملنے سے انکار کر دوں گی۔‘‘
ثمینہ غصّے میں آ گئی اور اَسد خاموش ہو کر سوچنے لگا۔
’’یہ جسے مذاق سمجھ رہی ہے، وہ تو میری زندگی کی سب سے اہم حقیقت بنتی جا رہی ہے۔
مَیں کیا کروں اِس لڑکی کا، یہ سمجھتی کیوں نہیں؟‘‘
ڈھکن کھلتے ہی ایک سیاہ پھنیر سانپ پھن پھیلائے لڑکی کی جانب بڑھنے لگا۔
ہجوم نے سانس روک لیے۔ منے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اُس کے سبھی دوستوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔
سانپ زور سے پھنکارا۔ پھر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ لپکا۔ لیٹے ہوئے بےبس شکار کے جسم میں اپنے دانت گاڑ دیے۔
لڑکی اُسی طرح اطمینان سے سیدھی لیٹی، چھت کی جانب دیکھتی رہی۔ یوں جیسے شامیانے کے اُوپر چھائے نیلے آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کے نغمے سن رہی ہو۔
شیشوں کی سیج سے تماشا گر کے پہنے ہوئے شوخ اور چمک دار کپڑوں کے رنگ منعکس ہوتے رہے۔ تالیاں بجتی رہیں۔ لوگوں نے کھل کر داد دِی اور تماشا گر باپ نے ہاتھ اُونچے کر کے ہجوم سے شاباش اور ڈھیر سارے نذرانے وصول کیے۔
اُس نے مہارت سے سانپ کو دوبارہ اُس گول ٹوکری میں بل دیتے ہوئے قید کر دیا ۔
بیٹی کو اُٹھ کر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ باپ کے چہرے سے پھوٹتی کامیابی کی خوشی اور فخر سے چوڑے ہوتے سینے کو دیکھ کر ننھی بٹیا بھی مسکرانے اور دَاد پانے کے لیے آگے آ گئی۔
ایسا تماشا کس نے پہلے کبھی کہاں دیکھا تھا؟ لوگ جوق در جوق اِس خاص اختتامی پروگرام کے لیے سرکس دیکھنے آنے لگے اور گاؤں کے ہر گھر میں اُس کا تذکرہ رہنے لگا۔
منا بھی گھر آنے کے بعد بار بار اَپنے امی ابو اور چھوٹے بہن بھائی کو اُس تماشے کے بارے میں بتاتا رہا۔ رات کو سویا، تو بھی اُس کے ذہن میں وہی نظارہ گھومتا تھا۔
کبھی اُس نے خود کو خواب میں سرکس کے اُونچے جھولے پر ڈنڈا تھامے محتاط قدم اُٹھاتے دیکھا۔
کبھی سانپ کے پھن کے مدِمقابل۔ پھر اُسے لگتا کہ وہ بہت سے کانچ کے رنگ برنگے ٹکڑوں کے عکس بین میں قید ہو گیا ہے ۔
کبھی ہاتھی کی کمر پر بیٹھا ہلکورے لیتا نظر آتا۔
منے کے دل و دماغ پر سرکس کا نیا تماشا بری طرح چھا چکا تھا۔
اتنی بہادر لڑکی۔ وہ سوچتا، تو اُسے جھرجھری آ جاتی۔ کتنے آرام اور مضبوطی سے اپنے جسم کو شیشوں کے ٹکڑوں پہ ٹکائے رکھتی تھی۔
کیا مہارت تھی واہ! ابو کے مفت پاسوں کی بدولت وہ دو تین بار سرکس سے ہو آیا تھا، مگر اُس تماشے کے فسوں سے آزاد نہ ہو سکا تھا۔
ایک روز سرکس کے پچھواڑے لگے بیری کے درخت پر پتھر مارتے، بیر توڑتے، وہ یکایک ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ اَپنے چھوٹے سے خیمے کے باہر کھڑی اُسے بیر توڑتی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔
منے نے نہ جانے کیوں بیروں سے بھری جھولی اُس لڑکی کی طرف اُچھال دی۔ وہ لپک کر آگے بڑھی اور بیر چُننے لگی۔
’’تمہارا نام کیا ہے؟‘‘ منے نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔
’’بلوری!‘‘ اُس نے مختصر جواب دیا اور اُس کی طرف دلچسپی سے دیکھنے لگی۔
’’ویسے مجھے سارے بلو کہتے ہیں۔‘‘
منا اُس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ اتنی روشن جیسے کانچ کے دو بنٹے ہرے سمندروں میں تیرتے ہوں۔ جیسے رات کے پچھلے پہر کے دو رَوشن دیے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہوں۔
’’تین بار تماشا دیکھ چکا ہوں تمہارا۔‘‘ منے نے اُسے فخریہ انداز میں بتایا۔
’’ابو نے پاس لا کر دیے تھے۔ بڑا مزہ آیا۔‘‘
’’اور تمہارا نام؟‘‘ بلوری نے بیر کی گھٹلی زمین پر تھوکتے ہوئے پوچھا۔
’’منا! اچھا بلو یہ تو بتا تجھے سانپ سے ڈر نہیں لگتا، تجھے درد نہیں ہوتا؟‘‘
منے نے پُرتجسس انداز میں سوالات داغنے شروع کر دیے۔
’’لو مجھے کیوں سانپ کے کاٹے سے درد ہو گا۔ مَیں سپیرے کی بیٹی جو ہوں۔
ابا کہتا ہے سانپ میرے بھائی ہیں۔ ہماری روزی ہیں، وہ مجھے پیار سے ڈستے ہیں، تو اِس لیے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اگر مَیں ہلوں، تو مجھے شیشہ چبھ جائے گا۔
بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ مَیں شیشوں کے اوپر نہیں بلکہ پھولوں کی سیج پہ لیٹی ہوں۔
نرم خوشبودار پھول میرے نیچے ہیں، جو اَماں کہا کرتی تھی ایک دن ضرور میرے بستر پہ بچھے ہوں گے۔‘‘
’’اچھا! وہ کب؟‘‘
’’جب میری شادی ہو گی اور کب۔ جب مَیں دلہن بنوں گی، تب تو کتنا اچھا لگے گا۔‘‘
’’بلو، او بلو پتر! کہاں دفع ہو گئی ہے؟‘‘
اُس کے باپ کی آواز کان میں آئی، تو وہ جھولی میں بھرے بیر جھاڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔
منا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔
اُس روز کے بعد منا جب بھی بیری سے بیر توڑتا، تھوڑے سے چھپا کر ایک لفافے میں ڈال کر نیچے گرا دَیتا ۔
پھر چھپ کر دیکھتا۔ بلو موقع پاتے ہی آتی، لفافہ اٹھا کر بھاگتی، تو اُسے بڑا اَچھا لگتا۔
وہ اپنی اِس نیکی کی وجہ سے بڑا خوش رہنے لگ گیا تھا۔
’’لیکن مَیں سوچتا ہوں کہ تمہیں سانپ کاٹتا ہے، تو تم زندہ کیسے رہتی ہو؟
مجھے کاٹے ، تو مَیں تو بس گیا۔‘‘
ایک روز اُس نے مرنے کے انداز میں زمین پر گر کر دکھایا، تو بلو ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی۔
’’ارے بابا! مجھ پر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ بتایا تو تھا اُس دن۔ جب سے مَیں پیدا ہوئی ہوں، ابا مجھے روزانہ ایک سانپ سے ڈسواتا ہے۔ اماں لڑتی، تو کہتا تھا، تجھے نہیں پتا۔
اِس طرح اِس پر سانپ کے ڈسنے کا کبھی اثر نہیں ہو گا۔
اب اگر مجھے کسی دن سانپ نہ کاٹے، تو مَیں بیمار ہو جاتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، سارا جسم دُکھنے سا لگتا ہے۔‘‘ بلو بولتی چلی گئی۔
گئے زمانے کے راجاؤں نے سوچا کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ ہمارے دشمنوں کی شکتی ٹوٹ جائے اور مات اُن کا مقدر بنے۔
اُنھوں نے دیس کے چار کونوں سے ویدوں کو طلب کیا، بدھی مانوں سے سوال کیا، سپیروں سے صلاح مانگی کہ کوئی ایسا کارن کرو کہ بس ایسا ہی ہو، ہم ہار کا مکھ کبھی نہ دیکھیں۔
سیانوں نے سر جوڑے، بدھی لڑائی اور ایک تجویز راجہ کو پیش کی۔ کہنے لگے:
’’مہاراج! پرش کی شکتی کو جتنی آسانی سے ایک ناری توڑ سکتی ہے۔
کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ناری جاتی کے پاس جو شکتی ہوتی ہے، پرش اُس کا ہرگز مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔
آپ آگیا دیں، تو ہم اِس مقصد کے لیے خاص طور پر ایسی ناریاں پال پوس کر جوان کریں، جو آپ کی اِس اچھا کا پالن کریں۔‘‘
’’آ گیا ہے۔‘‘ مہاراج بولے۔
پھر گاؤں والوں نے اپنی بہت سی سپتریاں پیدا ہوتے ہی ماؤں کی گودوں سے لے کر مہاپروہت کی جھولی میں ڈال دیں جہاں بڑی عمر کی دیوداسیوں نے اُن کی پرورش کا ذمہ لے لیا ۔
دِن رات اِس کام میں جُت گئیں۔ راجہ کی اِس ننھی ناری فوج کو خاص خوراکیں کھلائی جاتیں، خوشبودار تیل، شہد اور پھولوں کے رس سے اُن کے نازک کامنی بدنوں کی مالش کی جاتی ۔
روزانہ ننھے ننھے سانپوں کا تھوڑا زہر حلق میں ٹپکایا جاتا کہ اُن کے لہو کے ساتھ رگوں میں وش بھی ٹھاٹھیں مارے اور جزوِ ہستی بن جائے۔
جوان ہونے تک اُن ناریوں کو وش کی ایسی عادت ہو جاتی کہ نہ ملنے پر اُن کا جسم ٹوٹنے لگتا۔ وہ تڑپتیں، مچلیتیں، منت کرتیں اور کسی پل چَین نہ پاتیں۔
یہ خوبصورت کنواری کنہیائیں پوری طرح تیار ہو جانے کے بعد راج محل کی سازشوں کا پتا لگانے کا کام کرتیں ۔ یدھ سمے دشمن کو تحفتاً بھیج دی جاتیں۔
جو بھی اُنھیں دیکھتا، ملن کی آرزو کرتا اور سمبندھ قائم ہوتے ہی نڈھال ہو جاتا کہ اُن وش کنہیاؤں کے جسم کے ہر مسام، ہر اَنگ سے وش پھوٹتا اور دُوسرے کو گھائل کر دیتا تھا۔
’’یار یہ لڑکیاں بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہیں۔ اِن کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ثمینہ کو دیکھو مجھے نو لفٹ کروائے چلی جا رہی ہے۔‘‘ اسد نے جاگنگ کرتے ہوئے اپنے ساتھی ندیم سے کہا۔
’’تجھے تو کہا ہے اُس کا خیال چھوڑ دے، کسی اور طرف دھیان کر۔
وہ دَیکھ یار گلابی کپڑوں والی لڑکی کتنی زبردست ہے۔‘‘
ندیم نے پارک میں سیر کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک کو تکتے ہوئے کہا اور خود کھی کھی کرنے لگا۔
’’کئی بار سوچتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤں، مگر نہ جانے کیوں بس کمزور پڑ جاتا ہوں۔
اُس کی بھوری آنکھوں میں چھپی بھید بھری اداسی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ اُسے بھول جاؤں۔‘‘
I think I really love her. (مجھے لگتا ہے کہ مَیں واقعی اُسے پیار کرتا ہوں۔)
اگلے دن اسد ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچا، تو چوکیدار نے اُسے دیکھتے ہی کہہ دیا: ’’بی بی گئی ہوئی ہیں۔‘‘
اسد ڈھیٹ بن کر گاڑی میں بیٹھا اُس کا اِنتظار کرتا رہا۔
وہ جب آئی، تو رات کے تقریباً تین بج رہے تھے۔
’’تم اِس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟‘‘ وہ دُرُشتی سے بولی۔
’’تمہارا اِنتظار، مگر تم کہاں رہ گئی تھی؟ مَیں پریشان ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟‘‘ وہ ملائمت سے بولا۔
’’دیکھو اسد! میرے لیے کوئی پریشان ہو، تو مجھے عجیب اور بےجا لگتا ہے۔
پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مَیں تمہیں بتا رہی ہوں۔‘‘
’’یہ تم اکیلی اِس وقت باہر کیوں تھی، خیر تو ہے؟‘‘
’’ایک ماڈل کا فوٹوشوٹ تھا۔ تمہیں پتا ہے میرا پارلر کا کام ایسا ہی ہے۔
اُس میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب پلیز تم گھر جاؤ، مَیں بھی بہت تھکی ہوئی ہوں۔‘‘
اُس نے اسد کو وہیں کھڑا چھوڑ کر گیٹ کھلوایا اور بےنیازی سے ہاسٹل کی عمارت کے اندر چلی گئی۔
سپیرے کی بیٹی کے تماشے کی خبر دور دُور تک پھیل چکی تھی۔
ایک روز گاؤں کے چودھری صاحب نے بھی سرکس جانے کی خواہش ظاہر کی۔
کانسٹیبل اکرم اُن کی نشستوں اور خصوصی دیکھ بھال کے انتظامات کرنے کے لیے متحرک ہو گیا۔ سرکس والے بہت خوش تھے کہ اتنی بڑی شخصیت اُن کا پروگرام دیکھنے آ رہی ہے۔
اُنھوں نے اُس روز خاص طور پر شامیانے کے اردگرد صفائی کروائی، پانی کا چھڑکاؤ کیا، جانوروں کو خوشبودار صابن سے نہلایا ۔ پنڈال کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا کر چودھری صاحب اور اُن کے ہمراہ آنے والے معززین کا انتظار کرنے لگے۔
مقامی اخبار کے رپورٹر اور فوٹوگرافرز بھی وقت پر پہنچ گئے۔ شو دیکھنے میں محو چودھری صاحب کی کئی تصاویر بنا ڈالیں۔
بلو کے باپ سپیرے نے شو سے پہلے اعلان کیا کہ آج مہمانوں کے لیے اِس تماشے میں حیرتوں کے مزید سامان ہوں گے، تو لوگ پہلے سے زیادہ متجسس ہو کر انتظار کرنے لگے۔
منا بھی اپنے ابو اور دِیگر تماشائیوں کے ساتھ مشتاق نظروں سے شیشوں کی سیج پر لیٹی بلو کی طرف دیکھنے لگا، جس کا جسم ابھی تک چادر کے نیچے چھپا ہوا تھا۔
آج نہ جانے بلو کیا کرنے والی تھی، وہ سوچے جا رہا تھا۔ سپیرے نے دھیرے دھیرے بین بجانی شروع کر دی۔
ایک مددگار نے آگے بڑھ کر بلو پر سے کپڑا سرکانا شروع کر دیا۔
بلو اُس روز بہت خوبصورت چمک دار مگر پہلے سے بھی زیادہ مختصر کپڑوں میں میک اپ کیے، زیور پہنے، بالکل سیدھی لیٹی نظر آ رہی تھی۔
ابا نے اپنی لیٹی ہوئی فرمانبردار بیٹی کے جسم پر بڑے سلیقے سے ایک تختہ بچھایا، تو ڈھول کی تھاپ مزید دھمک دار ہو گئی۔
بلو نے حیرت سے ابے کی طرف دیکھا، مگر ابا اُس وقت مصروف تھا۔
اِس لیے اُس کی آنکھوں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ سانپ نے ٹوکری سے برآمد ہو کر حسبِ معمول بلو کو ڈسا،
تو بلو روز کی طرح بےحس و حرکت پڑی چھت کو گھورتی رہی۔
مگر آج ابا نے سانپ کو واپس ٹوکری میں نہیں ڈالا بلکہ اُسے بلو کے جسم پہ بچھے تختے پر بٹھا دیا جسے کچھ مددگار ساتھیوں نے دونوں طرف سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔
پنڈال کی بڑی بتیاں بجھا دی گئیں اور ہلکی روشنی میں تماشائیوں نے دیکھا کہ پنجرے میں قید ایک نیولا بھی سانپ کے برابر بٹھا دیا گیا ہے۔
لوگ حیرت و مسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر سیٹیاں بجانے اور اُلٹی سیدھی آوازیں نکالنے لگے جس سے بلو کی آنکھوں میں مزید تحیّر پیدا ہوتا نظر آنے لگا۔
نیولے اور سانپ نے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے ہی حملے شروع کر دیے اور ایک دوسرے کو دبوچنے، کاٹ کھانے کے لیے کشمکش شروع کر دی۔
منے نے بلو کی طرف دیکھا، تو اُسے لگا جیسے وہ اِس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھی، لہٰذا اُس نے چیخنا اور کسمسانا شروع کر دیا۔
وہ ہلی، تو شیشوں پر ٹکا اُس کا جسم قطرہ قطرہ نیچے رسنے لگا۔ اُس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے زور زور سے حرکت شروع کر دی اور بلند آواز سے رونے لگی۔
’’ابا! میرے ہاتھ کھولو ۔ ابا …..‘‘ اُس نے رسیوں سے بندھے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر چلّانا شروع کر دیا، تو شور سے پنڈال گونج اٹھا۔ لوگ تالیاں بجانے لگے۔
منے کو نہ جانے کیا ہوا، وہ بلو، بلو پکارتا ہوا تیر کی طرح کرسی سے اٹھا اور اَپنی دوست کے قریب جا پہنچا۔ اُس کے اپنے گال بھی آنسوؤں سے تر ہو رہے تھے۔
اُس نے بلاسوچے سمجھے بلو کی رسیاں کھولنے کی کوشش شروع کر دی اور ہاتھ مار کر اُس کے جسم پہ لٹکا تختہ دور اُتار پھینکا۔
اُسے یہ بھی نہ پتا چلا کہ اِس ساری کارروائی میں اُس کے اپنے بازو میں ایک نوکیلا شیشہ دور تک گھاؤ بناتا گھستا چلا گیا ہے۔ ابا نیچے پٹخے گئے سانپ اور نیولے کو پکڑنے کے لیے اِدھر اُدھر بھاگنے لگا۔
پولیس کانسٹیبل اکرم الٰہی نے اپنے کاکے کے بازو سے خون نکلتے دیکھا، تو وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اُس کی طرف بھاگا اور خون بند کرنے کے لیے پٹی ڈھونڈنے لگا۔
بلو کے زخمی جسم اور شیشوں کے تربتر ہونے کے نظارے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے فوٹوگرافرز نے کھٹاکھٹ تصاویر کھینچنا شروع کر دیں اور اَخبار کے رپورٹر نے اپنا قلم اور کاغذ سنبھال لیا۔
’’اوئے یہ کیا بدتمیزی ہے؟‘‘ پولیس کانسٹیبل نے ڈنڈا گھمایا۔
’’مائی باپ! کیا بتاؤں، اِس مر جانی نے تماشے کا ستیاناس کر کے رکھ دیا۔ ایک ذرا سے نیولے سے ڈر گئی۔‘‘ بلو کے باپ نے بلو کو دھموکے لگانے شروع کر دیے۔
’’اوئے بدبختے! آج وڈے چودھری صاحب آئے ہوئے تھے۔ آج ہی تُو نے تماشا خراب کرنا تھا۔
کیا ہوتا اگر تیرا اَبا چار پیسے کما لیتا؟ نذرانے ملنے تھے آج بڑے بڑے۔ بزدل کہیں کی۔
بالکل اپنی ماں پہ گئی ہے۔ کمینی نہ ہووے تے۔‘‘ ابا بکے جا رہا تھا اور بلو روئے چلی جا رہی تھی۔
’’اوئے کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے۔ اِس بچی کو اسپتال لے کر جاؤ، اِس کی مرہم پٹی کراؤ۔‘‘
چودھری صاحب اپنی کرسی سے اٹھے کہ اب اُن کی مداخلت کا وقت بھی آ چکا تھا۔
تماشائیوں نے تماشا پورا نہ ہونے پر شور مچا مچا کر پنڈال سر پر اٹھا لیا اور کرسیاں توڑنے لگے۔
’’اوئے اِدھر آ۔‘‘ چودھری صاحب نے سپیرے کو بلایا۔
’’اوئے اتنا ظلم اِس معصوم بچی پر، اوئے حیا کر۔ یہ کوئی تماشا ہے؟ فٹے منہ تیرا۔‘‘
چودھری صاحب کی ڈانٹ سن کر سپیرا گھگھیا کر معافی مانگنے لگا۔
اُنھوں نے اِس وعدے پر اُسے معاف کر دیا کہ وہ بچی کا آئندہ اِس طرح تماشہ نہیں لگائے گا۔ اِسے سکول میں پڑھائے گا، اِس کا علاج کرائے گا۔
چودھری صاحب نیک دل تھے، صاحبِ اولاد تھے، اُنھیں بچی کا اِس طرح سے تماشا بننا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ سپیرے نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور بچی کو لے کر اسپتال چل دیا۔
اگلے روز منا حسبِ معمول سرکس کے پچھواڑے لگی بیری پہ چڑھنے کے لیے دوپہر کو بھاگ کر پہنچا، تو یہ دیکھ کر زمین اُس کے پیروں تلے سے نکل گئی کہ وہاں سرکس نام کی کسی چیز کا نام و نشان تک نہ تھا۔
ویرانی ایسے ڈیرے جمائے تھی جیسے وہاں کبھی کوئی ذی روح پھٹکا ہی نہ ہو۔
چولہوں کی بجھی سیاہ رَاکھ اور بچی کھچی ہڈیاں چچوڑتی ہوئی آوارہ بلیاں سامانِ زیست پہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہی تھیں اور بیری پھل سے لدی کھڑی تھی۔
اُس روز منے نے ایک بھی بیر نہ توڑا اَور چپکے سے نیچے اتر آیا، وہ پھر دوبارہ اُس طرف کبھی نہ گیا۔
ندیم کے کہنے پر اسد نے ثمینہ سے فیصلہ کن بات کرنے کی ٹھانی اور اُس کے ہاسٹل جا کر گیٹ کے باہر اُس کا انتظار کرنے لگا۔
ثمینہ کئی گھنٹوں کے بعد گیٹ پر نظر آئی، تو اُس نے سوچا کتنا اوور ٹائم کرتی ہے بےچاری۔
اگر یہ میرا ہاتھ تھام لے، تو اِس کے سارے درد دُور کر دوں گا۔ گھر والوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے میں اِس کی مدد کروں گا۔
چوکیدار کو سو روپے کا نوٹ تھما کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ثمینہ کے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد چپکے چپکے اُس کے کمرے کی طرف چل دیا۔
گھنٹی بجنے پر ثمینہ نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسد کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔
اسد نے اندر آ کر دیکھا، نفاست سے سجے ہوئے کمرے میں ہلکا پھلکا فرنیچر اور ایک چھوٹا سا ٹی وی سیٹ پڑا تھا۔ دیواروں پہ کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں جو شاید اُس کے گھر والوں کی ہوں گی۔
ثمینہ نے اُسے پاس پڑی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔
’’ثمینہ! یہ کیا ہے، تم کہاں غائب ہو؟ اپنا عادی بنا کر مجھے اپنے سے کیوں دور کر رہی ہو؟ میری جان! ختم کر دو یہ ملازمت۔
اتنی محنت کرتی ہو تم۔ مجھے اپنا خیال رکھنے دو۔ مَیں جانتا ہوں تمہیں بھی مجھ سے اتنا پیار ہے جتنا مجھے تم سے ہے۔
یہ جذبے حقیقی ہیں، تو پھر ہم کیوں اِنھیں جھٹلائیں؟‘‘
اسد بولتا چلا جا رہا تھا کہ ثمینہ نے اُس کے لبوں پہ انگلی رکھ کر اُسے خاموش کر دیا۔
’’جذبے ہی تو مصیبت بن جاتے ہیں۔‘‘ وہ بڑبڑائی۔
’’مَیں تمہیں مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہوں ثمینہ! پلیز مان لو میری بات۔‘‘
’’تم مجھے نہیں بچا سکتے اسد۔ مجھے اِس بات کا پورا یقین ہے۔‘‘ ثمینہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔
وہ اُٹھی اور غسل خانے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔
اسد نے کمرے کی چیزوں کو یونہی الٹنا پلٹنا شروع کر دیا ۔ دِیوار پر لگی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ ایک تصویر نے اُس کی رگوں میں لہو منجمد کر دیا۔
بلیک اینڈ وائٹ اخبار سے تراشی گئی تصویر میں ایک بچی سرکس کے شامیانے میں لیٹی چیخیں مار رَہی تھی ۔ ایک نوعمر لڑکا اُس کے جسم سے شیشے ہٹا رہا تھا۔ ٹائٹل پر لکھا تھا۔
’’راجن پور سرکس ۱۹۷۰ء‘‘
’’اوہ میرے اللہ! بلو۔‘‘ اسد نے غسل خانے سے نکلتی ثمینہ کو تقریباً جھنجھوڑ ڈالا۔
چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ اُن کے بدنوں میں لرزش اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔
ثمینہ بولی ’’منے! تم کہاں سے میری زندگی میں دوبارہ چلے آئے ہو؟ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔‘‘
’’بلو! بچپن سے لے کر آج تک۔ مَیں تمہارے خیال سے کبھی آزاد نہ ہو سکا۔ جانتی ہو تم؟‘‘
وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا۔
’’مگر میری دنیا نہیں بدل سکی اسد! مَیں اب بھی ہر رات شیشوں کی سیج پر لیٹتی ہوں ۔ سانپ مجھے ڈسنے آتا ہے۔‘‘
اسد نے غصّے اور حیرت سے اُس کی طرف دیکھا ’’کیا کہہ رہی ہو تم؟‘‘
’’اسد! میرے ابا اور بھائیوں کو خرچہ چاہیے۔ ایک عرصے سے بس سلسلہ حیات یونہی چل رہا ہے۔ اَب تو عادت ہو گئی ہے۔‘‘ بلو کی آنکھوں سے نیلا سمندر بہ نکلا۔ اسد منجمد ہو گیا، اُسے کہنے کو کچھ سُوجھ نہیں رہا تھا۔
’’یہ کیا بات ہے، تم پڑھ لکھ گئی تھیں نا ۔ کچھ اور کر سکتی تھی، فیملی سپورٹ کے لیے۔ لڑکیاں ملازمت کرتی ہیں، ہزاروں کام ہیں۔‘‘
’’ہاں مگر منے! تم جانتے ہو مَیں تماشہ گر کی بیٹی ہوں۔ میری ساری زندگی ایک تماشا رہی ہے۔ مجھے کسی اور کام میں اتنے پیسے نہیں مل سکتے تھے۔‘‘ ثمینہ نے طنز اور دُکھ بھرے لہجے میں جواب دیا۔
’’مس ثمینہ گل! مَیں نہیں مانتا کسی بھی تاویل کو۔‘‘
’’اسد! ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بھوک ہے اور بھوک ایک سانپ ہے۔
جب یہ سانپ پھن پھیلا کر ڈسنے آتا ہے، تو ایمان، عقیدے، دھرم، فلسفے، سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اُس کا زہر عقلیں، نسلیں، رشتے سب چاٹ جاتا ہے۔
کوئی نہیں بچتا اُس کے ڈنگ سے، کوئی نہیں۔‘‘
وہ ہذیان بکتی جا رہی تھی۔ ’’
تمہیں گھن آ رہی ہے نا، ہم غربت کی ڈسی ہوئی لڑکیاں بڑی مجبور ہوتی ہیں منے۔
ہم سے نفرت نہ کرو، ہمیں معاف کر دیا کرو۔‘‘
’’ثمینہ! میری زندگی تو ایک خوش رنگ، خوش ذائقہ فرحت بخش جام تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟‘‘ اسد شاکی لہجے میں اُس کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑانے لگا۔
’’سوری! مگر کچھ لوگوں کے لیے زندگی بِس کا پیالہ ہوتی ہے جسے وہ گھونٹ گھونٹ پی کر جیے جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔
مَیں جانتی ہوں اسد! اب تم منے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو، لیکن ایک بار پھر کیا تم بلو کو؟ ‘‘
ادھوری بات نے بلو کے لبوں پہ دم توڑ دیا۔ اسد نے غصّے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا ۔
اُس کے کمرے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کی بار وُہ بلو کو نہیں بچا سکے گا۔