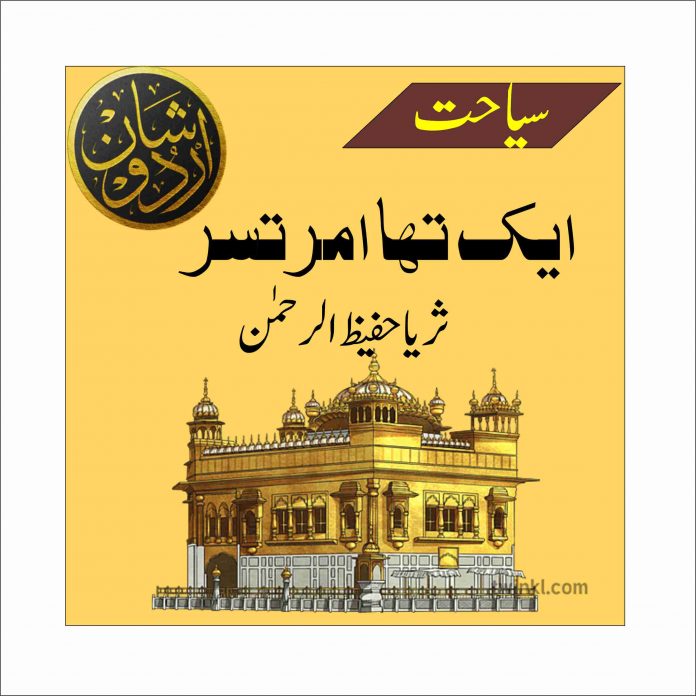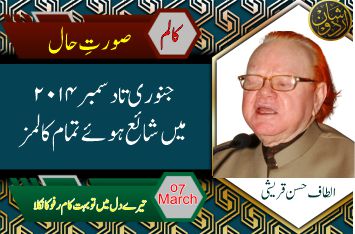ایک تھا امرتسر
ثریا حفیظ الرحمٰن

واہگہ بارڈر سے امرتسر اَڑتیس کلومیٹر دُور ہے۔ پاکستان سے بھارت جانے والوں اور بھارت سے واہگہ بارڈر تک پہنچنے کے لیے امرتسر سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ شروع شروع میں ٹیکسی میں واہگہ سے امرتسر تک کا کرایہ چالیس روپے سے ساٹھ روپے تک تھا جو بتدریج بڑھتے بڑھتے سو روپے تک پہنچ گیا۔ تب تک امرتسر کے سارے راستے کھلے تھے۔
واہگہ سرحد عبور کرنے والے اکثر لوگ ایک رات کے لیے امرتسر میں رُک جاتے۔
شہر میں داخل ہونے کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ صرف وقت کا خیال رکھنا پڑتا کہ ویزے سے زیادہ مدت نہ ٹھہرا جائے۔ مسلمان مسافر کشمیریوں کے ڈھابوں سے کھانا کھاتے یا کسی ہوٹل میں ٹھہر کر سبزیوں سے بنے کھانوں سے پیٹ بھرتے، سستی شاپنگ کرتے اور آگے روانہ ہو جاتے۔
یہ اُن دنوں کی بات ہے جب امرتسر میں چیزیں، دہلی سے نسبتاً سستی مل جاتیں۔ بھارتی مصنوعات، جعلی کشمیری شالیں اور سلک کی ساڑھیاں، کشمیری لیبل کے ساتھ عام دستیاب تھیں۔ امرتسر میں کشمیری مسلمان گنتی کے تھے جو یا تو جموں، سری نگر سے مزدوری کرنے کے لیے آتے اور زَیادہ تر سامان ڈھونے کا کَام کرتے۔ عرفِ عام میں انھیں ’’ہاتو‘‘ کہا جاتا، یا کچھ کشمیری مسلمان چھوٹا موٹا کاروبار چلا رہے تھے۔
ان میں زیادہ تر کشمیری اپنے چھوٹے چھوٹے کرائے کے ڈھابے چلاتے تھے جہاں سے پاکستان آنے جانے والوں کو پکا ہوا حلال گوشت اور دَال، سبزی، کلچہ وغیرہ مل جاتا۔ ورنہ واہگہ سے لے کر پنجاب، ہریانہ اور دہلی کے قرب و جوار تک حلال گوشت ناپید تھا۔ بھارتی پنجاب کو تو سکھّوں اور ہندوؤں نے 1947ء ہی میں ملیچھ مسلمانوں سے ’پوتر‘ کر دیا تھا۔ ہزاروں کو موت کے گھاٹ اُتار دِیا اور باقیوں کو بےسر و سامان بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ البتہ اَسّی ہزار کے قریب مسلمان خواتین اور بچیاں اپنی ملکیت میں رکھ لیں۔
سکھ بھی گوشت کھاتے ہیں، لیکن وہ جھٹکا کرتے ہیں۔ آج کل ہندوؤں، سکھّوں کا نوجوان طبقہ زیادہ گوشت خور ہو گیا ہے۔ یہ لوگ سوّر کا گوشت بھی بکثرت کھاتے ہیں، نیز سوّر کی چربی کا استعمال بھی عام ہے۔
امرتسر کے لوگ امرتسر کو ’امبرسر‘ کہتے ہیں۔ امرت کے معنی آبِ حیات اور سر کے معنی تالاب کے ہیں۔ یہ تالاب ہر مندر (گولڈن ٹیمپل) میں واقع ہے جس کا پانی امرت کہلاتا ہے۔ امرتسر میرے پُرکھوں کا شہر ہے۔ جب پاکستان معرضِ وجود میں آیا، اُس وقت اگرچہ ہم لوگ امرتسر میں نہیں تھے، لیکن مجھے اپنی دادی ماں کا گھر خوب یاد تھا۔ لاہور سے چلے، تو آپی جان نے کہا: ’’ٹھنڈا تالاب، کالی ماتا کا مندر پوچھ لینا۔ بازار ٹوکریاں والا ہے اور اَگر دُوسری سمت سے جاؤ، تو کٹڑہ سفید سے جانا۔ ٹوکریوں والے بازار میں، موڑ پر چاچا سیلو کی پھلوں کی دکان ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ گلی اندر جاتی ہے جہاں لوہے کے دو چھوٹے چھوٹے گارڈر لگے ہیں۔ اندر جا کر بائیں ہاتھ کو پہلی سے دوسری گلی ہے۔ پتہ نہیں چاچا سیلو زندہ بھی ہے یا نہیں اور مجھے یہ بھی تو علم نہیں کہ وہ ہندو تھا یا مسلمان۔ عیدگاہ کے پچھلی طرف تایا ابو کا گھر بھی دیکھ کر آنا۔ تمہیں تو کچھ یاد بھی نہ ہو گا۔ خیر دادی ماں کے گھر کا تجھے ضرور پتہ چل جائے گا۔ گھر کی پچھلی دیوار مسجد کے ساتھ لگی ہے۔ گھر نہ پہچان سکو، تو مسجد سے سمجھ جانا۔ گلی کے آگے بڑا سا پختہ ٹائلوں والا میدان ہے۔ امرتسر میں ہاتھی دروازہ بھی ہے جہاں بابا کے بہت سے رشتےدار رَہتے تھے۔ بگھیاں والا کٹڑہ بھی ہے۔ فخراں کی گلی بھی ہے جہاں سب ہمارے اپنے ہی لوگ رہتے تھے۔‘‘

سائیکل رکشا پر انسانی بوجھ
ہمارے ہم سفر دہلی میں ہمارے علاقے کے ایک موٹے سردار جی اور اُن کی پتنی تھے۔ وہ لوگ پاکستان میں پنجہ صاحب کی یاترا کے لیے گئے تھے اور ہمارے ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ امرتسر میں سائیکل رکشا دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ اگرچہ دہلی میں سائیکل رکشا دیکھ چکے تھے۔ پتلی ٹانگوں والے کمزور و ناتواں آدمی سائیکل رکشا کھینچتے ہوئے سانس لینے کے لیے بالکل جانور کی طرح پورا منہ کھول لیتے ہیں۔ رکشے پر بیٹھنے کے خیال ہی سے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ گلیوں اور بازاروں میں زرتار ساڑھیوں کے پلو اُڑاتی خوبصورت کھترانیاں سائیکل رکشاؤں میں بیٹھی پاس سے گزرتی جا رہی تھیں۔ بڑی توندوں والے لالہ جی اپنی توندیں سنبھالے، صحت مند سردارنیاں اوڑھنیوں سے سر ڈھانپے اور پگڑیوں والے سردار جی رکشاؤں میں آ جا رہے تھے۔
مائی سیواں کا بازار، سیوا سمتی، سنگِ مرمر کے سفید میناروں والی مسجد ….. اور مسجد کے ساتھ دادی اماں کا گھر ….. چھت پر کھلنے والا روشن دان …..! میرے ذہن میں ہر چیز گڈمڈ ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہمارے ہم سفر نے تین عدد سائیکل رکشا رکوا لیے۔ چھوٹا بیٹا تو اپنے ابو کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا اور بڑا بیٹا دوسرے رکشے میں میرے ساتھ ….. میں نے ایک ہاتھ سے رکشے کی کمانی کا سہارا لیا اور دُوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا کندھا تھامے رکھا۔ ہر آدھے منٹ پر میں سیٹ سے کھسک کر نیچے گرنے والی ہو جاتی اور ساتھ ہی میرا بیٹا بھی۔ بمشکل ہم دونوں اپنے آپ کو سنبھالتے۔ بازاروں اور گلیوں سے گزرے، تو بچپن کی ایک بھولی بسری باس نے گھیر لیا۔ یہ ناگوار باس بچپن کے کسی گوشے سے انگڑائی لے کر اُٹھی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ کسی بازار میں زیادہ ہو جاتی اور کسی میں کم۔ یہ ہینگ اور ہلدی کی ملی جلی باس تھی جو امرتسر کے بازاروں میں سے گزرتے ہوئے مشامِ جان کو معطر کر رہی تھی۔ایک پُرہجوم بازار سے گزرتے ہوئے گلہاٹی صاحب نے بتایا
’’یہ مائی سیواں کا بازار ہے۔‘‘ تھوڑی دور جا کر ایک دکان کے آگے رکشے رک گئے۔ سارے لوگ اُترے۔ دکان کے باہر لکڑی کے بینچ بچھے تھے۔ گلہاٹی صاحب نے ہمیں وہاں بٹھایا اور خود اَندر جا کر ٹھنڈا مشروب لے آئے۔ گولی والی بوتلیں تھیں، پینے میں نہایت بدمزہ۔ اندر سے مشین چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ بوتلیں بھرنے کی مشین لگی ہوئی ہے۔ گویا یہ ہول سیل ڈیلر کی دکان تھی۔ دکاندار گلہاٹی صاحب کا جان پہچان والا تھا۔ بازار میں خاصے ہجوم کے باوجود اُداسی چھائی تھی اور کوئی رونق نہ تھی۔ سپاٹ چہروں والے لوگ اپنے کاموں میں یوں مصروف تھے جیسے نیند میں کام کر رہے ہوں۔
’’یہ سیوا سمتی کیا ہوتی ہے؟‘‘ میں نے مسز گلہاٹی سے پوچھا۔ مائی سیواں کا بازار تو دیکھ چکے تھے، میں نے سوچا، لگے ہاتھوں سیوا سمتی سے بھی جان کاری ہو جائے۔
’’یہ ایک سبھا ہے۔ اس کے ماتحت بہت سے ادارے چلتے ہیں۔ ہسپتال، سکول، اناتھ گھر، پاٹ شالائیں وغیرہ، دھنوان پیسہ دان کرتے ہیں، ان سے یہ سمتی سارے ادارے چلاتی ہے۔ سیوا کا شوق رکھنے والے کرم چاری ان اداروں میں مفت سیوا کرتے ہیں۔
زخم خوردہ قافلے
وہاں سے ہم لوگ دوبارہ رکشا میں بیٹھ کر کالی ماتا کے مندر پہنچے۔ کئی گلیوں میں جھانکا۔ ایک دو گلیوں کے داخلی راستے پر لوہے کے گارڈر نصب تھے۔ دو عدد راستے ناپ کر، ہم لوگ تیسرے راستے کے فولادی ڈنڈوں کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھے، تو ایک چھوٹے سے پختہ میدان میں نکل آئے۔ واپس مڑ کر بائیں طرف کی گلیاں گنیں۔ بس ایک ہی تنگ و تاریک سی گلی کے آگے سے گزرے تھے۔ دوسری کے دہانے پر پہنچے جو پہلی والی سے تھوڑی کشادہ تھی۔ اِدھر اُدھر دیکھا تو گلی کے پہلے نکڑ پر ایک مکان کی بند چوبی گیلری نے جھک کر سرگوشی کی کہ یہ مسلمانوں کی گلی ہے۔ بند گیلری کے سامنے والا تین چار منزلہ مکان ایسے زمین بوس تھا جیسے زلزلے نے تباہ کر دیا ہو۔ چوباروں کی آدھی آدھی چھتیں کرم خوردہ ٹوٹی پھوٹی اندرونی الماریوں، کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے پٹ بھیانک منہ کھولے کھڑے تھے۔
آگے بڑھے تو ایک چھوٹا سا بوسیدہ مکان ثابت کھڑا تھا۔ اس کے سامنے والے دو مکان بھی بوسیدہ، مگر صحیح سالم تھے۔ آگے پھر تیسری منزل تک ملبے کا ڈھیر لگا تھا اور آگے بڑی بڑی نوساختہ عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دو تین مکانوں کے بعد گلی ختم ہو کر کھلا میدان بن گئی۔ واپس مڑے، چھوٹے مکان کے باہر والے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ جھانک کر دیکھا، تو ایک بزرگ سے آدمی کھاٹ پر بیٹھے تھے۔ ہمیں اجنبی جان کر باہر نکلے۔ گلہاٹی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر نمستے کہا اور ہمارا تعارف کرواتے ہوئے، ہمارا بتایا ہوا پتا پوچھا۔
’’آپ بالکل صحیح پتےپر کھڑے ہیں، بالکل ٹھیک جگہ پر۔‘‘ بزرگوار نے خوش دلی سے بتایا ….. دُور دُور تک دیکھا، کسی مسجد کا کوئی منار یا کوئی گنبد نظر آیا نہ کسی مسجد کی چھت پر کسی مکان کا روزن کھلتا دیکھا۔ میں دو تین مرتبہ آگے کی طرف گئی، پھر پیچھے لَوٹی ….. لیکن بےسُود۔ کھنڈروں کی ایک دنیا آباد تھی جس کے درمیان ایک سال خوردہ انسان ہمیں راستہ بتا رہا تھا۔ جہاں سے ہمارے آباؤ اجداد کے زخم خوردہ قافلے گزر چکے تھے۔ کوئی ملال کوئی تاسف نہ ہوا …… کہ مسلمان اللہ کی زمین پر جہاں آباد ہو جائے، وہی اس کی عارضی رہائش گاہ ہے۔
’’سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اور ہم نے اُسی کی طرف لَوٹ جانا ہے۔‘‘ ہاں اِتنا افسوس ضرور ہوا کہ ’’یہ کیسی قوم ہے جو اِتنے سال بیت جانے کے بعد بھی اجڑے ہوئے دیار بسا نہیں سکی، لیکن دہلی تو اٹاٹوٹ آباد ہے۔ ضرور کوئی گھپلا ہے۔‘‘
مجھے یاد آیا یہ شہر تو سعادت حسن منٹو کا شہر ہے جو میرے بابا کے کلاس فیلو تھے اور بعد میں میرے چچا کے ساتھ پڑھتے رہے۔ منٹو جنہوں نے سکول کے زمانہ ہی میں روسی زبان کی کتابوں کے ترجمے کرنے شروع کر دیے تھے۔ میرے بابا کہتے تھے منٹو انگلش کے پرچے میں نناوے فی صد مارکس لیتے، لیکن حساب میں دس بارہ نمبروں سے کبھی آگے نہ بڑھے۔ انگریزی زبان ان کے کسی کام نہ آئی، وہ بیچارے ساری زندگی حساب کتاب کے چکر میں ہی پس گئے۔ بنیے کی ہمسائیگی میں منٹو جانے کیوں حساب میں کمزور رَہے، لیکن وقت نے بتایا ہے کہ امبرسر والے تو ہمیشہ ہی سے حساب کتاب میں پستے رہے۔
1947ء میں سکھّوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کا حساب چکایا ….. ایسا چکایا کہ قصہ ہی پاک کر دیا اور اب ہندو، سکھّوں کا حساب کتاب چکا رہے ہیں اور سکھ ہندوؤں کا ….. اِس میں بےچارے منٹو کا کیا قصور ….. یہ تو سارا فساد امبرسر کا ہے۔
میرے بابا کے ایک اور کلاس فیلو ڈاکٹر سراج الدین بھی امبرسر کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر (سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے والد) بھی امبرسرئیے تھے۔ امبرسر اے۔حمید (معروف ادیب) کا بھی شہر تھا جو گُلوں کی باتیں کرتے، خوشبوؤں کی باتیں، پشمینے کی شالوں کے دھاگوں جیسے نرم الفاظ سے کہانیاں بُنتے اور نمکین چائے کے سماواروں سے محفلیں سجاتے۔ امبرسر میں ناریاں اب بھی سندر ہیں۔ سیبوں جیسی سرخی و سفیدی ذرا کم ہے، لیکن دِل رُبائی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔
دربار صاحب کی یاترا
ہم لوگ رام باغ کی ایک ماڈرن کالونی میں ایک سردار جی کے ہاں ٹھہرے تھے۔ بنگلہ خوبصورت تھا، مگر ابھی بن رہا تھا۔ رہائشی کمرے اور لاؤنج بن کر فرنیشڈ ہو چکے تھے۔ گلہاٹی صاحب نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ آج دوپہر کے بعد دربار صاحب جانا ہے۔ اُنھوں نے وہاں ماتھا ٹیکنا اور ہولی ڈِپ یا پوتر غوطہ بھی لینا تھا۔ ہمیں بھی گولڈن ٹیمپل دیکھنے کا شوق تھا۔ موسم ابھی خنک تھا۔ غسلخانے میں اِدھر اُدھر دیکھا، گیزر کہیں نظر نہ آیا۔
اچانک نل کے ساتھ اُوپر کو نظر پڑی۔ ایک چھوٹا سا اِنسٹنٹ گیزر لگا تھا۔ ہم لوگوں نے ایسا گیزر پہلے کبھی استعمال نہ کیا تھا۔ اِدھر اُدھر سے معائنہ کیا، آف آن کر کے دیکھا، نل کو چلایا تو گرم پانی بالٹی میں گرنے لگا۔ سوئچ بند کیا اور پھر نل چلایا، تو پانی ٹھنڈا یخ۔ واہ نہ بجلی کا ضیاع نہ پانی کا۔ کفایت کا یہ آلہ بڑ اپسند آیا۔ کفایت شعاری کنجوسی کی حد تک ہندوؤں میں پائی جاتی ہے۔ وہ سکھ فیملی بھی خاصی کفایت شعار محسوس ہوئی۔
انڈیا نے بجلی کی مصنوعات میں خاصی ترقی کر لی ہے۔ تقریباً ساری ہی چیزیں خود بناتے ہیں، لیکن بہت مہنگی۔ کار ہی لے لیں، مورس کار، جس کا نام ایمبیسڈر ہے، تب ایک لاکھ روپے میں ملتی تھی جبکہ جاپانی ٹیوٹا چالیس پچاس ہزار میں مل جاتی تھی۔ خیر ہم تیار ہوئے اور سائیکل رکشا پر سوار ہو کر گولڈن ٹیمپل پہنچے۔ اب سائیکل رکشے پر بیٹھنے کے کچھ کچھ آداب آ گئے تھے۔
ٹیمپل کی بارہ راہداریوں میں لوہے کے لمبے لمبے پائپ لگا کر ایک راستہ بنایا گیا تھا جہاں کھڑے ہو کر جوتے رکھوائے جاتے۔ لڑکے بالے، جوان اَور بوڑھے سکھ لوگوں کی جوتیاں صاف کرنے میں لگے تھے۔ معلوم ہوا کہ مفت سیوا ہے۔ لوگ گرد آلود میلی جوتیاں رکھوا کر جاتے، واپسی پر انھیں صاف اور پالش شدہ جوتیاں ملتیں۔ ایک طرف نل لگے تھے، نیچے حوضیاں بنی تھیں۔ لوگ ہاتھ دھوتے، کُلّی کرتے اور سر پر رومال باندھ لیتے۔ بیبیاں دوپٹوں سے اچھی طرح سر ڈھانپ لیتیں اور سب ننگے پاؤں سنگِ مرمر کے زینے چڑھ کر برآمدوں میں پہنچتے۔ وہاں سے چاروں اطراف سے زینے نیچے کو اُترتے تھے۔
عورتیں، مرد زینوں اور فرشوں کی صفائی میں لگے تھے جو یاتریوں کی راہ میں ذرا بھی مزاحم نہ ہوتے۔ سیوا کرنے میں چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ ہر کوئی اپنی خوشی سے سیوا میں جُتا ہوا تھا۔ کوئی سردارنی اپنی اوڑھنی سے زینہ پونچھ رہی تھی، تو کوئی صاف ستھرے تنکوں کی نئی نکور جھاڑو سے کام لے رہی تھی۔ ایک جوان ناری سر کے اُوپر بڑا سا رومال رکھے اپنے لمبے بال کھولے اُن سے جھاڑو کا کَام لے رہی تھی۔ ایک بچہ اپنی نئی قمیص سے فرش دھو دھو کر پانی نچوڑ رَہا تھا۔ سچی عقیدت اور لگن کے نظارے دیکھنے والے تھے۔
برآمدے اور زِینے سب سنگِ مرمر کے بنے تھے۔ زینہ اُتر کر دُور تک سنگِ سفید کا فرش بچھا تھا۔ چاروں طرف سفید دھواں سا اُٹھتا نظر آ رہا تھا۔ درمیان میں ایک بڑا پانی کا سروور (تالاب) تھا جو لبالب گدلے پانی سے بھرا تھا۔ ٹھہرے ہوئے پانی کی ناگوار باس ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تالاب کے چاروں اطراف پوتر غوطہ لینے والوں کی سہولت کے لیے بےشمار لوہے کے کنڈے آویزاں تھے۔ گلہاٹی صاحب تو فوراً کپڑے اُتار کر کنڈے کے سہارے پانی میں اتر گئے۔ چُلّو میں پانی لے کر پہلے تو امرت چکھا اور پھر پانی میں غوطہ لگا کر اُبھرے۔
امرت چکھنا اِندرا گاندھی کا
حفیظ اور دونوں بچے قریب کے مرمریں بینچ پر بیٹھ گئے اور مسز گلہاٹی میرا ہاتھ پکڑے بائیں طرف زنانہ حماموں کی طرف لے گئیں۔ مرد و زَن کا بےپناہ ہجوم تھا۔ ایک حمام کے کھلے در میں سے بیبیاں لائن میں باری باری اندر جا رہی تھیں اور دُوسرے در سے اسی تسلسل سے واپس نکل رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے امرت چکھنے کی جگہ ہے۔ اندر حمام کی لمبائی میں ایک زینے کی سیڑھی بنی تھی اور حمام کا حوض پانی سے بھرا تھا۔ پانی حوض کی ایک دیوار کے نیچے سے باہر کے بڑے سروور میں سے براہِ راست اندر کی طرف تیر رہا تھا۔ عورتیں زینے پر کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ کے چُلّو میں پانی لیتیں اور ناک تک لے جا کر منہ میں ڈال لیتیں۔ اسے امرت چکھنا کہتے ہیں۔
مسز گلہاٹی نے مارے عقیدت کے ایک چلو بھر کر میرے دائیں ہاتھ پر بھی ڈال دیا اور کہا کہ یہ امرت ہے۔ اسے چکھنے سے بڑا ثباب (ثواب) ملتا ہے اور سو بیماریاں دور ہوتی ہیں۔
میں نے مسز اِندرا گاندھی کو فلم میں گولڈن ٹیمپل میں امرت چکھتے دیکھا تھا۔ میں بھی مسز گلہاٹی کا دل رکھنے کے لیے چُلّو ناک تک لے گئی اور پھر بےاختیار اسے اِس طرح حرکت دی کہ کچھ پانی نیچے زینے پر گر گیا اور کچھ میرے ڈوپٹے پر پڑا۔ مجھے یوں لگا جیسے ناک کے نزدیک سے سڑی ہوئی مچھلیوں کا ٹوکرا گزار دِیا گیا ہو۔ بُو نے سارے وجود کو ہلا دیا، پِتہ اچھل کر منہ کو آنے لگا۔ میں نے منہ اور ناک کو ڈوپٹے سے دبایا اور بھاگ کر تعفن زدہ حمام کے دوسرے دروازے سے باہر آ گئی۔ مسز گلہاٹی بھی میرے ساتھ ہی باہر نکل آئیں۔ ادھیڑ عمر، جہاں دیدہ مسز گلہاٹی سمجھ گئیں اور بڑی ملائمت سے فرمایا کہ سروور مدت سے صاف نہیں کیا گیا۔ اب صفائی کا انتظام ہو رہا ہے۔ پر آپ جانیں ہمارے دھرم میں، اِس پوتر جل کو چکھنے سے پاپ جھڑتے ہیں اور وَاہ گورو کی کرپا سے بڑی شانتی ملتی ہے۔ باہر سروور میں سینکڑوں سردار اَور بچے ہولی ڈپ لے رہے تھے۔
میں واپس آ کر حفیظ اور بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ دو ایک ابکائیاں آ ہی گئیں۔ تیزی سے میں نے پرس کھولا اور میٹھی سونف اور چار پانچ الائچیاں اکٹھی ہی پھانک لیں۔ مسز گلہاٹی دوسرے حمام میں اشنان کرنے جا چکی تھیں۔ زنانہ حماموں میں نہانے کے لیے جو حوض بنے تھے، ان میں بھی باہر والے سروور ہی کا پانی رواں تھا۔ تالاب کی طرف حماموں کی دیواریں نیچے سے کھلی تھیں اور تالاب کے پانی کے اُوپر پُل کی طرح بنائی گئی تھیں تاکہ سروور کا پانی براہِ راست اندر آتا جاتا رہے۔ جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے قریب ہی لوگوں کے ٹھٹ گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔
جھانک کر دیکھا سروور کے کنارے ایک درخت کا خشک ٹھنٹھ تھا۔ معلوم ہوا کہ اسے ’’دکھ بھجنی بیری‘‘ کہتے ہیں، دکھ دور کرنے والا بیر کا درخت۔ سکّھوں کا عقیدہ ہے کہ اِس بیری کے پھل، پتے اور چھال میں سے کچھ بھی کھانے سے ہر مرض دُور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوڑھ کا مرض بھی۔ دو ایک ٹہنیوں کے ساتھ درخت بالکل خشک تھا لیکن لوگ مارے عقیدت کے ہاتھ لگا لگا کر چوم رہے تھے۔
ہمارے ہم سفر ہولی ڈپ سے فارغ ہو کر آ گئے تھے۔ سبھی عورتوں نے ڈوپٹوں سے سر پوری طرح ڈھانپے ہوئے تھے اور آدمیوں نے سروں پر رومال باندھ رکھے تھے۔ گلہاٹی صاحب نے دربار صاحب کے باہر ہی حفیظ اور بچوں کے سروں پر رومال بندھوا دیے تھے۔
دربار صاحب میں داخلے کے کچھ آداب اور ضابطے ہیں۔ سیاح لوگ شرومنی گوردوارہ پربندھک کمیٹی کے دفتر سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ جوتے، استعمال شدہ موزے، چھتری، چھڑی،اسلحہ، منشیات اور تمباکو وغیرہ کی ممانعت ہے۔ اسلحہ رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دربار صاحب کے بارہ پربندھک کمیٹی کے دفتر میں ایک رجسٹر پر اسلحہ کی تفصیل درج کروا کر اسلحہ دفتر میں جمع کروا دیں اور لَوٹتے ہوئے اسے واپس لے لیں۔
سونے کی پلنگڑی پر گرنتھ
اب گلہاٹی صاحب نے ہمیں ٹیمپل کا اصل حصہ جو باہر سے سارا سونے کا بنا ہے، دکھانے لے چلے۔ انھوں نے خود انھی گرنتھ صاحب کے درشن کرنے اور ماتھا ٹیکنا تھا۔
تالاب کے اُوپر پُل عبور کر کے ہم سب لوگ بڑی مشکل سے اندر دَاخل ہوئے۔ بھیڑ اِس قدر زیادہ تھی کہ اندر پہنچنا دشوار نظر آتا تھا۔ گولڈن ٹیمپل کا یہ حصہ ہرمندر کہلاتا ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف سونے کے سنہرے پترے چڑھے ہیں۔ عمارت کے اوپر بڑا سا کلس بھی سونے کا ہے۔ کئی گیلریاں عبور کر کے ایک گیلری میں پہنچے۔ سونے کی ریلنگ کے اندر کی طرف ایک چوکور کٹہرے کے اندر سونے کے پائیوں والی ایک پلنگڑی کے اوپر گرنتھ صاحب کا نسخہ رکھا تھا۔ نسخہ بہت بڑے صندوق کی طرح تھا۔ اس کے اُوپر ساٹن کا گوٹے والا رومال اسے پوری طرح ڈھانپے ہوئے تھا۔ دو گرنتھی، دائیں بائیں، مورچھل کر رہے تھے۔ فرش رو دُودھیا سفید چادریں بچھی تھیں۔ ایک طرف کیرتن پارٹی بیٹھی تھیں۔ پاس ہی ہیڈگرنتھی آنکھیں موندھے بیٹھے تھے۔
گرنتھ صاحب کی پلنگڑی کے پاس سفید چادر پر سکّوں اور نوٹوں کا ڈھیر لگا تھا۔ کٹہرے کے باہر گیلریوں میں بھی دودھیا چادریں بچھی تھیں۔ سارے ستون اور گیلریاں سنگِ سفید سے بنی تھیں۔ ایک طرف عورتیں سر جھکائے عقیدت سے بیٹھی تھیں اور اَیک طرف مرد ہاتھ جوڑے عاجزی سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ماحول نہایت پُرتقدس، عاجزانہ اور پُرسکون تھا۔ ہلکے سُروں میں دل میں اُتر جانے والی دھیمی موسیقی کی سریلی آواز میں گوروبانی کا پاٹھ ہو رہا تھا۔ کیرتن کی آواز کے سوا کسی کے سانس لینے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں صرف چند لمحوں کے لیے کیرتن کی آواز بند ہوتی ہے، وہ بھی جب کیرتن پارٹی بدلتی ہے۔
گولڈن ٹیمپل کی بنیاد ایک مسلمان ولی میاں میر صاحب نے رکھی تھی، بلکہ سکّھوں کے ایک گورو نے خود دَرخواست کر کے اُن سے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رَکھوائی تھی۔ دراصل بابا گورونانک نے تو واحدانیت کا ہی سبق دیا تھا۔ گرنتھ صاحب کے زیادہ تر اشلوک اور دَوہے بابا فرید گنج شکرؒ کے کلام پر مشتمل ہیں۔ ہندوؤں نے بڑی کوشش کی کہ گرنتھ صاحب سے بابا فریدؒ کا کلام نکلوا دیا جائے، لیکن سکّھوں نے ان کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں۔
لوگ ننگے پاؤں بےآواز قدموں سے آ رہے تھے۔ گرنتھ صاحب کو ماتھا ٹیکتے اور حسبِ توفیق سکّے اور نوٹ دان کرتے۔ نوٹوں اور سکّوں کے دو الگ الگ ڈھیر خاصے اُونچے تھے، سفید چادر پر الگ پڑے تھے۔ گرنتھی لوگ انھیں ہاتھوں سے ایک طرف ہٹا رہے تھے۔ ساتھ ساتھ نوٹ اور سکّے الگ کرتے جاتے۔ گوردواروں میں روزانہ ہزاروں کی آمدن ہوتی ہے، لیکن گولڈن ٹیمپل میں تو آمدنی کا کوئی حساب ہی نہیں۔ بڑے سے لے کے بچے تک روپیہ پیسہ دان کرتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ پھر سکھّوں کے لیے رفاہی کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ مدتوں تک ہندو براہمن گوردواروں کا سرپرست بن کر سارا دھن سمیٹتا رہا۔ اَب بھی ہندو گورنمنٹ ہر گوردوارے سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے۔
تقریباً آدھ گھنٹہ وہاں بیٹھ کر ہم لوگ باہر نکلے۔ تالاب کے پُل پر سیوا میں جُتے لڑکے، جوان اَور بوڑھے سکھ کڑاہ پرشاد وَالے تھال اُٹھائے کھڑے تھے اور ہر گزرنے والے کو حلوے کا ایک دونا (پتوں سے بنا پیالہ) پکڑا دَیتے۔ گرم گرم حلوے سے نچڑتا گھی انگلیوں سے چاٹتے اور دھکم پیل کرتے یاتری گزر رَہے تھے۔ اُن کے سروں کے اُوپر سے خالی تھال تیزی سے واپس ہوتے اور بھرے ہوئے مزید آ جاتے۔ وہ اِتنی پھرتی سے کام کر رہے تھے کہ ایک بچے کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔
اب ہم کھلے صحن میں آ گئے۔ یہاں ایک طرف پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کی قطار لگی تھی جن کے نزدیک میز پر صاف ستھری چم چم کرتی کانسی کی کٹوریاں رکھی تھیں۔ یاتری حماموں سے پانی بھر کر پیتے اور کٹوریاں دوسری طرف فرش پر ڈھیر کرتے جاتے۔ نیچے پیڑھیوں پر معزز بیبیاں بیٹھی ریت سے جھوٹی کٹوریاں صاف کر کے میز پر لگائے جاتیں۔ پانی صاف و شفاف اور ٹھنڈا تھا۔ سامنے ہی ایک تین منزلہ عمارت تھی جو اکال تخت کہلاتی ہے۔ آپریشن بلیو اسٹار سے پہلے سنت جرنیل سنگھ بھنڈراں والا اَکال تخت کی تیسری منزل پر رہتے تھے۔ دوسری منزل پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے کی اشیاء رکھی تھیں۔ ایک کمرے میں متبرک اشیاء سجی تھیں، دروازے پر تالہ پڑا تھا۔ ہفتے میں ایک مقررہ دن پر تالہ کھلتا ہے اور لوگ گوروؤں کی متبرک اشیاء کے درشن کرتے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل کے متعدد دَروازے مختلف بازاروں میں کھلتے ہیں۔ داخلے کا بڑا دروازہ گھنٹہ گھر کی طرف سے ہے۔ اسی طرف سامنے گوردوارہ بابا ٹل ہے۔
دربار صاحب سے جب واپس باہر نکلے، تو جوتے پہن کر ٹیمپل کے ساتھ ساتھ ایک بازار میں جا نکلے۔ ہر طرف روشنیاں پھیلی تھیں۔ کِھلے ہوئے چہرے اور دھنک کے رنگ بکھرے تھے۔ دکانیں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ جھلملاتی ریشمی چوڑیوں کے ڈھیر، رنگ برنگی چُنیاں، چمکیلے نگینوں والے زیورات، بازار کی چکاچوند سے آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ زندگی سے بھرپور قہقہے تھے، کھنکھناتی آوازیں تھیں۔ دکانیں سنہرے چمکیلے سامان سے بھری ہوئی تھیں۔ کھلے ہاتھ پاؤں اور چوڑے چہروں والی سردارنیاں، خوش رو جوان سردار، صاف رنگت والے بچے اور بچیاں، جن کے چہروں سے خوشی پھوٹی پڑتی تھی۔ سارے بازار میں خریداری ہو رہی تھی۔ بازار گولڈن ٹیمپل کے ایک اور دَروازے تک سجا ہوا تھا۔
جلیانوالہ باغ بھی دیکھنے گئے۔ باغ کیا ہے، ایک چھوٹا سا پارک ہے جسے تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پارک کے چاروں طرف، لوہے کی ریلنگ لگی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سبز گھاس کے قطعے۔ ایک آدھ فوارہ، کچھ پھولوں کی جھاڑیاں اور بیٹھنے کے لیے ایک دو چبوترے! وہ کنواں بھی دیکھا، جو جلیانوالہ سانحہ کے وقت لاشوں سے پٹ گیا تھا۔
گردونواح کے قدیم مکانوں کی نانک شاہی اینٹوں میں گولیوں کے نشانات محفوظ کر لیے گئے تھے۔ باغ کے نواح کے رہنے والے بچے ٹولیوں میں باغ میں کھیل کود رَہے تھے۔ ایک طرف ایک بڑا بورڈ لگا تھا جس پر سانحہ جلیانوالہ باغ کا سنِ عیسوی اور کچھ واقعات گورومکھی اور انگریزی میں لکھے تھے۔
امرتسر کا باڑہ، پاکستانی مال
ریلوے اسٹیشن کے پیچھے امرتسر کی باڑہ مارکیٹ واقع ہے جہاں پاکستانی مصنوعات کھلے عام بکتی ہیں۔ کپڑا، کولر، ہاٹ پاٹ، تھرماس، کراکری، پلاسٹک کے برتن، الیکٹرک گڈز، گھی آئل وغیرہ۔ یہاں کرنسی کا کَاروبار بھی ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر اندر، باہر پاکستانیوں، سکھّوں اور ہندوؤں کی بھیڑ رہتی ہے۔ بھارتی مسلمان، پاکستانی مسلمان اور آگے پیچھے ’جی مہاراج‘ ….. جی مہاراج کرتے ہوئے دھیمے مزاج والے ہندو اَور گرم جوش سردار جی!
امرتسر میں منوچاجی بھی رہتے تھے، سردار منوچاجی جو بالکل مسلمانوں کی طرح کھلے دل سے ملتے۔ امرتسر سے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ ہی اپنے ہاں بلاتے۔ پلنگوں پر سفید چادریں بچھا کر ان پر بٹھاتے۔ نئے نکور سفید اور کالے دھاگے سے بنے ہوئے کھیس بچھا کر دسترخوان لگواتے اور خالص ویجیٹیرین کھانا کھلاتے۔ چمچماتے کانسی کے کٹوروں میں لسی پلاتے۔ دیش کی بنی ہوئی پیالیوں میں سونف ملی چائے پیش کرتے۔
ہمارے امرتسر پہنچنے پر خود اسٹیشن پر ہمارا ستقبال کرتے اور بڑے چاؤ سے گھر لے جاتے۔ اُن کے بیٹے، بیٹیاں، اُن کی پتنی بڑھ بڑھ کر سواگت کرتیں۔ اپنے دُکھ سُکھ اور امرتسر سے گزرنے والے پاکستانیوں کی باتیں کرتے۔ پاکستان ٹی وی کے پروگراموں پر تنقید اور تعریف و توصیف کھلے دل سے کرتے۔ پاکستان ٹی وی کا ایک ایک اشتہار اُن کی فیملی کو ازبر تھا۔ اُنھیں پاکستانی ٹی وی کے دھارمک (مذہبی) پروگرام سب سے زیادہ پسند تھے۔ قرآنِ کریم کی تلاوت ہو رہی ہو یا بچوں کو قرآنِ پاک کی آیات سکھائی جا رہی ہوں، وہ لوگ سارے پروگرام دیکھتے۔
درسِ قرآن کے سکھ شیدائی
ان کی بیٹی روزی ایم اے کی طالبہ تھی۔ ہر وقت سر پر ململ کا موٹا دوپٹہ اوڑھے رکھتی۔ بڑے چاؤ سے ملتی۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے بڑے غصہ میں کہا: ’’آنٹی جی! اگر آپ کی عورتیں پاکستان ٹی وی پر مولانا اسرار اَحمد کو برداشت نہیں کر سکتیں، تو ٹی وی مت دیکھا کریں۔ لیکن انھیں دوسروں کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا آپ ہمارا یہ سندیسہ مولانا اور ٹی وی کے بڑے کرمچاریوں تک پہنچا سکتی ہیں کہ ہم لوگ مولانا کا پروگرام بہت پسند کرتے، دیکھنا چاہتے اور ان کی باتوں کو سمجھنا اور اَپنانا چاہتے ہیں۔‘‘
روزی کا بھائی جو اُن ہی دنوں انجینئرنگ کا کورس مکمل کر کے اپنے گھر آیا تھا، اُس نے بھی بڑے جوش و خروش سے انگریزی میں کہا
’’مذہب اور اخلاقیات صرف مسلمانوں کی میراث نہیں، یہ ورثہ سب انسانوں میں بانٹنا چاہیے۔ آپ مسلمان تو مساوات کے عَلمبردار بنتے ہیں۔‘‘
’’پاکستان والے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پڑوس کا ملک، ان کے سنتوں عالموں سے کچھ حاصل کر لے۔‘‘ روزی نے پھر غصے اور اَپنائیت سے لقمہ دیا۔
مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے دہلی کے قیام کے دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن پر مولانا ڈاکٹر اسرار اَحمد کا پروگرام ہوا کرتا تھا جس سے ہماری پاکستانی ماڈرن بیبیاں الرجک تھیں اور مولانا کی پاکستان ٹی وی سے چھٹی کروانے کا غلغلہ تھا جس کا شور پاکستان کے ہمسایہ ملک کے سرحدی علاقوں میں بھی سنا گیا اور جسے وہاں کے لوگوں نے بالکل پسند نہ کیا۔ بات عجیب تھی کہ مولانا اپنے ملک میں تو تنقید کی زد میں تھے اور بھارتی پنجاب اور کشمیر میں بےحد مقبول۔
ایک سردار جی نے کہا: ’’آپ لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا کہ مولانا کا پروگرام بند کروا دِیا۔ جس دن مولانا اسرار اَحمد کا پروگرام ہوتا، تو ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے جوان، بوڑھے سبھی جلد جلد کام نمٹا کر سرِشام ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے۔ ہماری مُنّیوں نے تو باقاعدہ چُنّیاں لینی شروع کر دی ہیں اور اپنے بالوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا ہے۔ دھرم کوئی بھی ہو۔ اچھی باتیں سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں۔‘‘
ایک سردارنی نے فرمایا: ’’مولانا کی باتیں دل موہ لیتی ہیں، من کو شانتی دیتی ہیں۔ اُنھوں نے تو ہمارے من ہی بدل دیے ہیں۔ پرماتما کی دیا سے ایک اچھے مہاتما کی باتیں سننے کو ملتی تھیں اور ہم پوری کوشش کرتے کہ اُن کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کر کے ثباب (ثواب) لیں۔‘‘
ایک جوان لڑکے نے کہا: ’’ہم تو پاکستانیوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ مولانا ہمیں سچی روشنی دکھاتے ہیں۔‘‘ اور ایک سکھ لڑکی نے امرتسر میں مجھ سے بڑے تاسف سے کہا
’’افسوس آپ کی بیبیاں کچھ زیادہ ہی ماڈرن بننے کے چکر میں ہیں۔ ہمیں آپ لوگ کافر کہتے ہیں۔ کافر تو آپ کی بیبیاں ہیں جو بال کٹوا کر ننگے سر ننگے منہ سارے بازار میں گھومتی ہیں۔ آپ کی بیبیوں نے مولانا کا پروگرام بند کروا کے ہم لوگوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم تو سچی روشنی، سچی لگن کی تلاش میں ہیں۔ من کی شانتی چاہتے ہیں، دلوں کا کھوٹ دور کرنا چاہتے ہیں۔ بےحیائی سے بچنا چاہتے ہیں۔‘‘
میزبانی ہندوؤں کی
امرتسر کلب میں بھی جانا ہوا۔ امرتسر میں ہماری ایک دوست ہندو فیملی رہتی تھی، یش اور کرن اَروڑا۔ ایک مرتبہ ہم پاکستان جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک اور پاکستانی فیملی بھی سفر کر رہی تھی۔ مسز راس مسعود اَور اُن کے تین عدد بچے۔ راس مسعود بھی دہلی میں تعینات تھے۔ ٹرین میں ساتھ کے کیبن میں یش فیملی بھی اپنے دو بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اُنھوں نے سب سے پہلے میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ دوستی بڑھائی اور ساری معلومات حاصل کیں، اور پھر عائشہ (مسز راس مسعود) سے اپنا تعارف کروایا، مگر عائشہ نے کچھ التفات نہ کیا اور میرے کان میں کہا کہ یہ سب ویزے کا چکر ہے۔ آپ بھی بات آگے نہ بڑھنے دیں، لیکن مسز کرن ایش اُٹھ کر ہمارے کیبن میں آ گئیں اور اَپنا تعارف کروا کر ہمارے پاس بیٹھ گئیں۔
امرتسر اسٹیشن پر اُترے، تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ صبح سات بجے کا ٹائم تھا اور ہمارا اسٹیشن ہی پر ناشتہ کرنے کا پروگرام تھا۔ امرتسر سے واہگہ تک ٹیکسی ایک گھنٹے میں آسانی سے پہنچا دیتی۔ یش فیملی کی کار اُنھیں لینے آئی ہوئی تھی۔ ہمیں پوچھے بغیر ہی اُنھوں نے ٹیلی فون کر کے اپنے گھر سے ایک عدد مزید گاڑی منگوا لی۔ یش اور کرن ہمارے سر ہو گئے کہ ناشتا ہمارے گھر چل کر کریں۔ اُنھوں نے اِتنا اصرار کیا کہ ہمیں مجبوراً جانا پڑا۔
یش نے کرن اور ہم دونوں عورتوں اور بچوں کو کار میں بٹھا کر پہلے روانہ کر دیا اور خود دُوسری گاڑی کے انتظار میں رک گئے۔ شہر سے خاصا دُور اُن کے بنگلے کے آگے کار رُکی۔ ہم برآمدے ہی تک پہنچے تھے کہ یش ہمارے دونوں بیٹوں اور حفیظ کو لے کر پہنچ گئے۔ کرن مجھے، عائشہ اور اس کے بچوں کو سیدھا اپنے کمرے میں لے گئیں۔ حفیظ اور بیٹوں کو یش نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کرن نے جلد جلد اپنے چھوٹے بچے کی آیا کو کچھ ہدایات دیں اور خود ڈرائی فروٹ وغیرہ سے ہماری خاطر مدارت میں لگ گئی۔ سب کے ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہونے تک ڈائننگ روم میں ناشتہ لگ گیا۔
امرتسر پر گھٹا خوب چھائی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا تھا۔ موسلادھار بارش راستے میں شروع ہو گئی تھی۔ گھر پہنچنے تک چھاجوں مینہ برسنے لگا۔ امرتسر کی بارش تو مشہور ہے۔ اِتنے میں بجلی بھی چلی گئی۔ دسمبر یا غالباً جنوری کا مہینہ تھا۔ سخت سردی میں خنک کمرے، بجلی کا ہیٹر لائٹ کے ساتھ ہی بند ہو گیا تھا۔ آیا نے کمرے میں موم بتیاں جلائیں۔ میں اور عائشہ، کرن کو اپنے ہاں کی سوئی گیس سے متعارف کرانے لگیں۔ اور دِل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رَکھا ہے، لیکن ہم ناشکرے پاکستانی، بےپناہ نعمتوں کے باوجود ناآسودہ، اپنے حال پر گلے شکوے کرنے والے، اپنے وطن کو برا بھلا کہنے والے اور اَغیار کو سہلانے والی قوم بن چکے۔
آدھ گھنٹہ بجلی کے آنے کا انتظار کیا، لیکن بےسُود۔ ناچار اندھیرے ہی میں موم بتیوں کی روشنی میں ناشتہ کیا۔ کالے بادلوں کی وجہ سے گھٹا ٹوپ اندھیرا رَات کا سماں پیش کر رہا تھا۔ اُوپر سے کڑاکے کی سردی۔ کرن کا پنڈت رسویا، بارش کو کوسنے دیتا، گرم گرم پوریاں، بھاگ بھاگ کر میز پر پہنچا رہا تھا۔ دو تین قسم کا حلوہ، مٹھائی اور کیک، میز پوری بھری تھی۔ ہم لوگوں نے گرم گرم پوریاں اور کچوریاں کھائیں۔ حلوے کا ایک آدھ چمچ لیا اور گرم گرم کافی معدے میں اُنڈیلی، مگر ٹھنڈ دُور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
پُرتکلف ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ برآمدے میں نکل آئے۔ اُوپر کی منزل سے کرن کے جیٹھ اور جیٹھانی بھی پشمینے کی شالوں میں لپٹے اُتر آئے۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، تو پاکستان پر باتیں ہونے لگیں۔ معلوم ہوا کہ یش کے بھائی اور بھابھی چند دن پہلے پاکستان کی یاترا سے واپس آئے تھے اور پنڈی باڑہ میں اُوں نے جی بھر کر شاپنگ کی تھی۔
یش برادران کی امرتسر میں سوپ فیکٹری تھی۔ کرن بھی دہلی کے فرشتہ سوپ فیکٹری والوں کی بیٹی تھی جو ہر روز ایک نئی پشمینہ کی شال اوڑھتی اور وہائٹ گولڈ سے لدی پھندی رہتی۔ اس کا باپ سورگ باش ہو چکا تھا اور وِدھوا ممی فیکٹری کا کَاروبار سنبھالے تھی۔ اس کی جیٹھانی بڑے پُرغرور انداز میں باتیں کر رہی تھی اور جیٹھ رام راجیہ کے سپنے میں لیٹا اور مہا بھارت کا ارجن بنا اپدیش دے رہا تھا: ’’دھرتی کے سب باسی ایک ہیں۔‘‘
موسلا دھار بارش رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ یش صاحب حفیظ اور دونوں بیٹوں کو لے کر سوپ فیکٹری دکھانے چلے گئے جس میں چاول کی بھوسی سے تیل نکال کر صابن بنایا جاتا تھا۔ میں اور مسز مسعود اَب پریشان ہونے لگیں۔ لاہور میں ہم لوگوں نے اپنے پہنچنے کی اطلاع کی ہوئی تھی۔ خیر تیز بارش ہی میں ہم لوگ واہگہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کرن اور یش نے ہماری واپسی کے ٹکٹ رکھوا لیے اور وَعدہ لیا کہ ہم لوگ واپسی پر بھی ان لوگوں سے مل کر جائیں گے۔
میرا اَور حفیظ کا دل نہ چاہا کہ ان سے بےاعتنائی کی جائے۔ واپسی پر میں بادام اور کینو کی کچھ پیٹیاں دہلی میں اپنے پڑوسیوں اور ملنے جلنے والوں کے لیے لے کر آئی تھی۔ سوچا کہ ایک پیٹی کرن اور یش کو بھی دیتے چلیں۔ اسی رات ہمیں بذریعہ ٹرین دہلی بھی پہنچنا تھا۔ یش اور کرن شدت سے ہمارے آنے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ سہ پہر کو ہم لوگ پہنچے۔ شام کو یش اور کرن ہمیں امرتسر کلب لے گئے۔ گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ دونوں پاکستان کے متعلق معلومات لیتے رہے۔ لاہور دیکھنے کے وہ بڑے مشتاق تھے۔ رات کا کھانا کلب سے سنیک وغیرہ لے کر پورا کیا۔ ڈرتے ڈرتے صرف مچھلی ہی منگوائی اور سبزی کا سوپ پیا۔ ان لوگوں نے بڑا اِصرار کیا کہ مٹن کا بنا ہوا کچھ کھا لیں۔
دراصل نان ویج ہندو ہر قسم کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ چاہے وہ سؤر کا ہو، بکرے کا یا گائے کا، انھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے انھیں بتایا کہ ہم لوگ صرف حلال گوشت کھاتے ہیں۔ انھیں حلال و حرام کا فرق بتایا، تو وہ کچھ حیران ہوئے۔
مسلمان عورتوں کی سکھ اولاد
’’دہلی میں میری ممی کے ہاں جو گوشت پکتا ہے، وہ بڑے مزےدار ہوتا ہے۔ ویسا مزےدار گوشت امرتسر میں نہیں ملتا۔ ممی شاید مسلمانوں کی دکان سے منگواتی ہیں اور یہاں تو سکھ لوگ بیچتے ہیں جو نہایت گندے ہوتے ہیں۔ تبھی ان کے ہاں کا گوشت اچھا نہیں ہوتا۔‘‘ کرن نے ناک سکیڑتے ہوئے بتایا۔ وہ حلال و حرام کو بالکل سمجھ نہیں پائی تھی۔
پھر سکھّوں کی باتیں ہونے لگیں۔ ’’یہ نہایت گندی اور جنگلی قوم ہے۔ انھوں نے سارے ملک کو گندا کیا ہوا ہے۔ بالکل لٹیرے، چور اَور ڈاکو ہیں۔‘‘ دونوں نے بڑی نفرت کا اظہار کیا: ’’ہم تو انھیں بالکل منہ نہیں لگاتے۔‘‘
’’ہم نے تو سنا تھا کہ سکھ لوگ بڑے چوڑے چکلے، لامبے اور بڑے رف قسم کے جانگلی ہوتے ہیں، لیکن آج کل کا نوجوان سکھ تو خوش شکل اور دَھان پان سا ہے۔ اگر ڈاڑھی نہ رکھیں، تو بڑے وجیہہ نظر آئیں۔‘‘ میں نے باتوں ہی باتوں میں کرن سے کہا۔
وہ ایک دم چونکی۔ ’’یہ تو مسلمانیوں (مسلمان عورتوں) کی اولادیں ہیں۔ دیکھا نہیں سکھنیاں کتنی سندر ہیں۔ آپ جانیں، مسلماننیاں تو بڑی کومل اور سندر ہوتی ہیں۔ ان جانگلیوں نے 1947ء میں مسلمانوں کی ہزاروں لاکھوں عورتیں اور سپتریاں چھین کر اپنے گھروں میں ڈال لی تھیں۔‘‘ کرن نے میرے کان میں سرگوشی کی ’’یہ سب ان کے پتر، پتریاں ہیں۔‘‘
یہ بات میں پہلے بھی دہلی میں اکثر ہندو عورتوں سے سن چکی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ہماری امی ہمیں سنایا کرتی تھیں کہ 1947ء سے پہلے ہمارے والد صاحب پنجاب میں کہیں تعینات تھے۔ جس علاقے میں انھیں گھر ملا، وہاں زیادہ تر سکّھوں کے مکان اور حویلیاں تھیں۔ کرائے کا مکان بھی ایک سکھ کی ملکیت تھا۔
اتفاق سے پڑوس میں جو حویلی تھی، وہاں ایک وڈیرے سردار کی بیوی مسلمان تھی جس نے میری امی کے ساتھ دوستی کرنی چاہی تھی لیکن امی اس سکھ کی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ نفرت سے تھوک دیتیں اور کہتیں کہ وہ عورت ضرور بدچلن ہو گی جو سکھ کی بیوی بنی بیٹھی تھی۔ وہ بتاتی تھیں کہ سکّھوں کے اکثر گھروں میں ایک بھائی بیاہ کر دلہن لے آتا ہے اور وہ باقی سب بھائیوں کی مشترکہ دلہن ہوتی۔ اکثر سکھ کنوارے ہی بوڑھے ہو جاتے یا گیانی بن جاتے تھے۔
کلب میں بھی زیادہ تعداد سکھ نوجوانوں کی تھی۔ بہت سے لوگوں کے باوجود کلب میں ذرا رونق نہ تھی۔ در و دیوار سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ لوگ مدھم روشنی میں مےنوشی میں مشغول تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے والی دیوار کا رنگ بھی بالکل سیاہ تھا اور اس پر کسی دیوی کا ڈراؤنا سر سجا تھا۔ کالے چہرے پر سفید آنکھیں تھیں۔
ہمیں دہلی پہنچے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک سہ پہر تین بجے کے قریب کسی خاتون کا ٹیلی فون آیا
’’نمستے بہن جی، میں کرن کی ممی بول رہی ہوں، امرتسر والی کرن کی۔ یش اور کرن آج کل یہاں دہلی میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ آپ کے ہاں آنا چاہتے ہیں۔‘‘
’’ویلکم‘‘ میں نے کہا۔ ’’آج شام آ جائیے۔‘‘
شام کو کرن، اس کی ممی اور ایک آنٹی آئیں۔ میں نے یش کا پوچھا، تو انھوں نے بتایا کہ یش ہمارے ہی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، اِس لیے ساتھ نہیں آ سکے۔ انھوں نے بتایا کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہیں۔ ہمیں یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ کرن نے پاکستان دیکھنے کا ذکر امرتسر ہی میں کر دیا تھا۔ اس کی جیٹھانی پاکستان یاترا کر آئی تھی۔ بھلا کرن پیچھے کیوں رہ جاتی؟ لیکن قصہ صرف کرن اور یش کے جانے کا نہیں تھا۔ وہ تو سارا خاندان جس میں بارہ تیرہ لوگ تھے، سب اکٹھے جانا چاہتے تھے اور وَہ بھی لاہور …..
اُن دنوں ہندوؤں کے لیے دھرم استھانوں کی یاترا کے لیے بھی ویزے جاری نہیں ہوتے تھے۔ ادھر یش فیملی کے کوئی رشتہ دار بھی لاہور میں نہیں رہ رہے تھے جو اُن سے ملنے کے بہانے ہی ویزہ جاری ہو جاتا۔ ان کی قسمت ….. !
ہندو اَور لاہور کی سندرتا
انھی دنوں لاہور میں کرکٹ میچ ہونے والا تھا۔ ایمبیسی سے دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی پُرزور اپیل پر ایک آدھ روز پہلے ہی پاکستانی حکومت کی طرف سے ویزہ جاری کرنے کی عام اجازت مل چکی ہے۔ حفیظ نے دوسرے دن پاکستانی سفارت خانے سے ان سب کو ویزے دلوا دیے۔ کچھ دنوں کے بعد امرتسر سے ہمیں شکریے کا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا:
’’ہم نے جی بھر کے لاہور کی سیر کی۔ امرتسر سے صرف اڑتیس کلومیٹر دُور ایک نئی دنیا دیکھ کر آئے ہیں۔ بڑی حسین ….. بڑی خوبصورت، بڑی ہی سندر دُنیا۔ اس کی سندرتا دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ ہم سے اِتنے تھوڑے فاصلے پر ایک نئی دنیا آباد ہے۔
اور یہی نئی دنیا ہم ہندوؤں کو دکھانا چاہتے تھے۔ خاص طور پر پنجابی ہندوؤں کو، جن کا خیال تھا کہ مسلمان ایک دن بھی پاکستان کو سنبھال نہ سکے گا۔ وہ پاکستان جس میں کاغذ، قلم اور دَوات تک نہ تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے پھلے پھولے، خوشحال پاکستان کو دیکھیں، صحت مند اور رَوشن چہروں والے لوگوں سے ملیں۔ ان بےیار و مددگار لُٹے قافلوں کے آبلہ پا خستہ و درماندہ مسافروں اور ان کی اولادوں کو دیکھیں کہ وہ اب کن جنتوں میں رہتے ہیں۔
آپریشن بلیو اسٹار پر ہندوؤں کی خوشی
بعد میں یش فیملی سے خاصی دوستی بڑھ گئی۔ کرن جب دہلی آتی، ضرور ملتی۔ اس نے دہلی میں اپنے ایک کزن کی شادی پر بھی ہمیں مدعو کیا۔ آپریشن بلیو اسٹار پر وہ بہت خوش تھے۔ خاص طور پر کرن۔ وہ ہمارے ہاں آئی، تو اس نے کہا
’’دیکھا ہم نے سکھّوں کو کیسا مزہ چکھایا؟ خالصتان مانگتے تھے۔ آئے دن یہ جانگلو وحشی ہمیں یعنی ہندوؤں کو دھمکاتے، آنکھیں دکھاتے، ہمارے معصوم و بےگناہ لوگوں کو قتل کرتے، گولیوں سے بھونتے، ہمارے گھروں میں ڈاکے ڈالتے، ہماری حکومت کا پیسہ لُوٹتے۔ ہمیں کہتے کہ پنجاب چھوڑ دو۔ دیکھا ہم نے اُن کا کیسا حساب چکایا ہے؟ وہ تو ہمیں پنجاب سے نکالتے تھے، ہم نے انھیں جگ سے ہی نکال باہر کیا اور ساتھ ہی ان کے نیتاجی بھنڈرانوالا کو سیدھا پرلوک بھجوا دیا۔‘‘
کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ کرن پھر دہلی آئی۔ تب جو ہمارے ہاں آئی، تو کچھ روہانسی تھی، کچھ پریشان ….. معلوم ہوا کہ امرتسر کے حالات اِتنے مخدوش ہو چکے کہ کرن کو اپنا بڑا بیٹا کَرن، نانی کے ہاں دہلی میں چھوڑنا پڑا اور خود اَپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ، ماری ماری کبھی دہلی اور کبھی امرتسر کے چکر کاٹتی۔ امرتسر میں بھرا پرا گھر بڑے بیٹے کے بغیر کاٹنے کو دوڑتا اور پھر گھر لُٹنے کا بھی خدشہ رہتا۔ وہ اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر دہلی میں مستقل آباد ہونے کا سوچ رہی تھی۔ یش بھی دہلی کے کئی پھیرے لگا چکے تھے اور اَپنے کاروبار کے متعلق نہایت فکرمند تھے۔ بےچاری یش فیملی، دیکھیں امرتسر کا حساب کتاب کب چکاتی ہے۔
پھر دیکھتے دیکھتے بھارت میں پنجاب پرابلم نے پنجاب کا راستہ غیرملکیوں کے لیے بند کر دیا۔ آپریشن بلیو اسٹار نے سب کچھ تہ و بالا کر دیا۔ امرتسر خون میں نہا گیا۔ ہندوؤں نے سکھّوں کو گولڈن ٹیمپل میں ان کے اپنے ہی خون میں ہولی ڈپ دے دیا تھا۔ توپوں کے دہانوں نے اتنی آگ اگلی کہ اس کے دھوئیں میں سارا شہر تاریک ہو گیا۔ گھبرو جوانوں کا شہر، بھوتوں کا شہر بن گیا تھا۔ گولیوں کی بارش نے سکھ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے سینے چھلنی کر دیے۔ فوجی گاڑیاں اور ٹینک امرتسر کا سینہ کوٹنے لگے۔
ہر طرف فوج کا راج تھا اور مشین گنوں کا راج ….. وہ دھنک رنگ جگمگ کرتی دکانیں، جھلملاتی چوڑیاں،رنگ برنگی چُنیاں اور پگڑیاں، چمکیلے نگوں کے ڈھیر، سب اندھیاروں میں ڈوب گئے۔ تاریکیاں پھیل گئیں، وحشت بڑھ گئی۔ بہیمیت نے پنجے گاڑ دیے۔
ہندو کہتا ہے سکھ مقابلے میں مارے گئے اور اِتنے سکھّوں نے خودکشی کر لی۔ وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ اس نے کتنے ہزار جوان اور سندر بالک، اپنی ناگن مہارانی اندرا براہمن دیوی کی بھینٹ چڑھا دیے۔ براہمن دیوی کی موت کے بعد سکھّوں نے ہندوؤں سے روٹی بیٹی کا ناتا توڑ لیا۔ اب شاید کبھی ان کی یکجائی نہ ہو۔ سکھّوں نے اپنا ناتا مرکز سے بھی توڑ لیا۔ اور وَہ اپنے ہی غم کی آندھیوں میں نڈھال ع
پتہ ٹوٹا ڈال سے پون اُڑائے جائے
1947ء کے خوں آشام دور پر پنجاب کی ایک سکھ بیٹی امرتا پریتم نے پنجاب کا نوحہ لکھا تھا۔
چھتیس سال بعد امرتا پریتم کی اپنی دھرتی کی ناگن نے اس کے بھائیوں کو ڈس لیا۔ اس کے بیٹوں کی رگوں میں زہر اُتار دِیا جس کو اس کے آباء نے اپنی دھرتی کی مہارانی بنایا تھا۔ اس کے بھائیوں نے مہارانی کے پریوار کو راج سنگھاسن پر بٹھایا تھا۔
اے بی بی امرتا پریتم! تیرے دیش واسیوں نے تیرے بیٹوں کو موت کی ناؤ میں بٹھا کر فنا کے گھاٹ اُتارنا شروع کر دیا۔ تیرے بیٹوں کو ہی نہیں بلکہ ان بدنصیب مسلمان ماؤں کے سکھ بیٹوں کو بھی نرک کے گھور اندھیاروں میں دھکیلنا شروع کر دیا جن کو تیرے بھائیوں نے 1947ء کی خون آشام دوپہروں میں ان کے پیاروں سے چھین لیا تھا۔ ان نرم و نازم کونپلوں، ان کومل کلیوں کو شاخوں سے نوچ لیا تھا۔ ان سوہنیوں کو ٹھنڈے پانیوں کے کناروں سے اُٹھا کر اپنی کچھاروں میں لے جا کر بند کر دیا تھا۔ وہ سکھ بیٹوں کی مسلمان مائیں۔ کیا ان ماؤں کی وہ المناک سزائیں کم تھیں…؟
جیون نے جو قطرہ قطرہ زہر ان کی سانسوں، ان کے رگ و پے میں ٹپکایا، کیا وہ زہر، وہ نوکیلے برچھوں کی انیاں ناکافی تھیں؟
آؤ امرتا پریتم، اب ایک نیا گیت لکھو، موت کا گیت۔ اپنے بھائیوں کی موت کا گیت، اپنے بیٹوں کی موت کا گیت، ایک نیا نوحہ لکھو۔ آنسوؤں سے بھرا نوحہ ع
ایک نیا بین لکھو، لہو بھرے پنجاب کا‘‘
٭٭٭